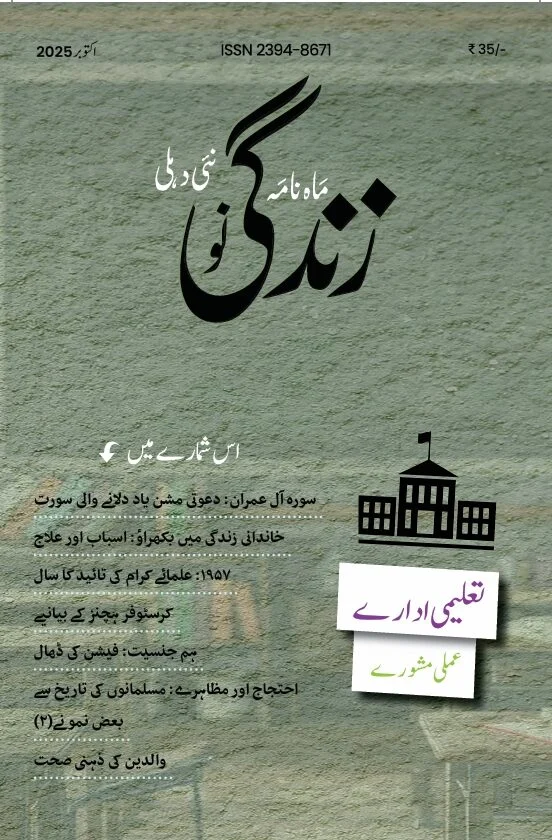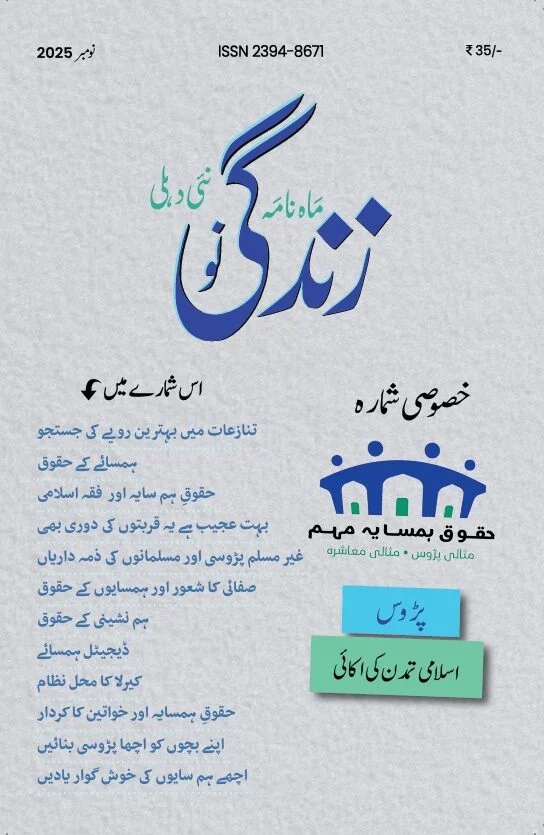احتجاج کےنت نئے انداز
سلاطین کی پالیسیوں اورکارگزاریوں کی مخالفت مختلف انداز سے کی جاتی تھی۔ کبھی کبھی ان کے خلاف ناراضی کا اظہاربھی ہوتا تھا اور ان پرتنقید و اعتراض بھی کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات صرف بددعاؤں اور رونے دھونے پر ہی اکتفا کر لیا جاتا تھا، اور بعض اوقات عوام کا ہجوم سڑکوں پر اتر آتا تھا اور علی الاعلان عوامی مطالبات پیش کیے جاتے تھے۔
بازاروں اور مسجدوں میں احتجاج
بعض احتجاجات عوامی مقامات، مثلاً مساجد اور سرکاری دفاتر یا عمارتوں کے قریب منظم کیے جاتے تھے۔ مظاہرین عوامی مقامات کو بند کر دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہاں کا کام کاج معطل ہو جاتا تھا، یا ہڑتال کے ذریعے بازاروں اور دکانوں میں تالے لگوا کرتجارتی وکاروباری سرگرمیاں معطل کر دی جاتی تھیں۔ احتجاج کا ایک طریقہ اپنے بعض مطالبات کو صاف انداز میں پیش کرنے کا بھی تھا۔ اس کے لیے درخواستیں لکھ کر متعلقہ حکام و اہل کار تک پہنچائی جاتی تھیں۔
کبھی کبھی مساجد یا بازاروں کے اندر یا باہر عام ہڑتال کا اعلان کیا جاتا تھا اور اس طرح سے حکومت کی سیاسی و معاشی پالیسیوں کے خلاف احتجاج درج کرایا جاتاتھا۔ امام ذہبی ’تاریخ الاسلام‘ میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ 352ھ/963ء میں بازنطینیوں نے دیار اسلام کے شہر حلب پر حملہ کر دیا اور شمالی عراق میں ان کے داخل ہوجانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یہ صورت حال حکومت کی طرف سے دشمن کے ساتھ تعاون کا عندیہ دے کر امت کے تئیں خیانت نہ بھی رہی ہو، تاہم حکومت حملہ آور کی اس جارحیت کو روکنے میں ناکام رہی، اس لیے مسلمانوں نے اسے حکومت کی کوتاہی وناکامی تصور کیا۔
امام ذہبی کہتے ہیں کہ جارحیت نے عوام کو آپے سے باہر کر دیا۔ لوگ حملہ آوروں کو روکنے میں حکومت کی ناکامی کے خلاف احتجاج کے طور پر باہر نکل آئے۔ اس پُر امن احتجاج کے تحت اہل موصل نے بازاروں پر تالے لگوا دیے اور جامع مسجد میں اکٹھا ہوگئے۔ وہاں سے ناصر الدولہ (ابن ابی الہیجاء الحمدانی م: 358ھ/969ء) کی طرف چلے۔ آخر کار ناصر الدولہ نے عوام کو دشمن کے خلاف مزاحمت کا یقین دلایا، جس کے بعد عوام احتجاج ختم کرکے ہڑتال موقوف کرنے پر راضی ہوئے۔
دارالخلافت بغداد کے باشندے بھی اپنے موصلی اور شمالی عراقی بھائیوں کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو گئے۔ انھوں نے ہڑتال میں شامل ہوتے ہی بازاروں کو بند کرنے کا اعلان کر دیا اور باب الخلافہ کی طرف نکل پڑے۔ ان کے ہاتھ میں ایک نامہ بھی تھا جس میں حلب کے مصائب وضاحت کے ساتھ تحریر کیے تھے۔ انھوں نے خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا: ’’ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ نکل کر نہ آئیں اور تمام علاقوں کو خط لکھ کر افواج کو جمع نہ کر لیں، ورنہ خود کو معزول کریں تاکہ کسی اور کو خلافت کی ذمے داری دی جائے۔‘‘ ان باتوں سے خلیفہ ناراض ہو گیا۔
362ھ/971ء میں پھر یہ صورت حال دہرائی گئی۔ طبری کے مطابق بازنطینیوں نے دوبارہ سے مسلمانوں کی سرحدوں پر حملہ بول دیا تو اس علاقے کے باشندے مدد کے لیے بغداد آئے۔ انھوں نے جامع مسجد میں جمع ہو کر ہنگامہ کیا، مسجدوں کے منابر توڑ دیے اور ائمہ کوخطبہ دینے سے روک دیا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ المطیع للہ (م:363ء/974ء) کے محل کی طرف بڑھے اور اس کی بعض کھڑکیاں توڑ دیں۔‘‘
اسلام اور صلیبی کشمکش کے زمانہ عروج میں ایوبی سلطان ملک معظم (م: 624ھ/1227ء)نے وہی لائن اختیار کی جو مسلمانوں کی نظر میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ خیانت اور شہر القدس کی توہین و تحقیر سے عبارت تھی۔
616ھ/1219ء کے آغاز میں اس نے صلیبیوں کے ڈر اور ان کے سامنے اپنی بے بسی کی وجہ سے بیت المقدس کی فصیلوں کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا تاکہ صلیبی اسے اپنی ملکیت نہ بنا سکیں۔ چناں چہ فصیلوں کے انہدام کا کام شروع ہوگیا۔۔۔۔ لوگوں نے چیخ پکار کی۔ باپردہ عورتیں اور بچیاں بھی باہر نکل آئیں، بزرگ، بوڑھے اور جوان سب گنبدالصخرہ اور مسجد اقصیٰ کی طرف نکل آئے۔۔۔۔۔ لوگوں نے ملک معظم کی اس نازیبا حرکت پر اس کی مذمت کی۔ (شذرات الذہب از ابن العماد حنبلی)
سیکیورٹی عملے کی زیادتیوں کے خلاف عوام کی طرف سے احتجاجی ہڑتال کی ایک مثال ذہبی نے نقل کی ہے کہ ’’513ھ/1119ء میں سلجوقی کمانڈر مَنْکُبَرس (م: 513ھ/1119ء) کو بغداد کے امن عامہ کا انچارج بنایاگیا۔ لوگوں کے ساتھ اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اس نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی اور رعایا کو پریشان رکھا۔ عوام نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس وقت تک بازاروں کو بند رکھا جب تک سلطان نے اسے واپس بلا کر قتل نہیں کر دیا۔‘‘
اقتصادی فیصلوں اور پالیسیوں کے خلاف ہڑتال کا طریقہ یہ تھا کہ احتجا ج کے طور پر مخصوص و متعین سامانوں کی خرید بند کر دی جاتی تھی۔ ابن بطوطہ (م: 779ھ/1377ء) اپنے سفرنامے میں ذکر کرتا ہے کہ سرزمین ہند میں زراعتی فصلیں مہنگی ہو گئیں تو خلجی سلطان نے سرکاری گودام کھول دیے اور سرکاری اناج کو بازار میں اتار کر قیمتوں کو سستا کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ غلّے کی قیمتیں بڑھ گئیں تو اس نے حکم دیا کہ حکومت کی متعین کردہ قیمت پر ہی اناج خریدا جائے۔ لوگوں نے اس قیمت پر خریدنے سے انکار کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص سرکاری گودام کے علاوہ کوئی دوسرا غلہ نہ بیچے۔
احتجاج اور مظاہرے کا ایک عجیب وغریب طریقہ یہ تھا کہ مسجدوں میں تالے لگا دیے جاتےتھے اور حکومت کو اپنے مطالبات ماننے پر مجبور کرنے کی غرض سے باجماعت نمازیں معطل کر دی جاتی تھیں۔
312ء/924ء میں بغداد کے اندر ابوطاہر الجنّابی قرمطی (332ھ/ 944ء) کی قیادت میں قرامطہ نے اس راستے کے تعین پر اعتراض کیا جدھر سے حجاج کے قافلے کو موسم حج کے اختتام کے بعد حجاز سے عراق آنا تھا۔ اس کے نتیجے میں 2500 افراد قتل کر دیے گئے جن میں تین سو خواتین تھیں۔
عفیف الدین ابن اسعد الیافعی (م: 768ھ/1366ء) نے ’مرآة الجنان‘ میں ذکر کیا ہے کہ قرامطہ نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ تلواریں ان کی گردنوں پر رکھ کر مال سے لدے ہوئے اونٹوں کو ہنکا لے گئے۔ لوگ بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ جو بچ گیا اس کی حالت بھی انتہائی غیر تھی۔ بغداد اور دوسرے علاقوں میں رونا پیٹنا مچ گیا اور لوگوں نے نماز کے لیےمسجدوں میں جانا ترک دیا۔‘‘
احتجاج کے طور پر لوگ اپنے مطالبات پر مشتمل عرضیاں بھی پیش کرتے تھے اور اپنے موقف و مطالبات کی وضاحت کے لیے علامتی وسائل اختیار کیا کرتے تھے جس طرح آج کل مظاہرین بھک مری کے اظہار کے لیے روٹیاں، دیگچیاں اور کھانے پینے کے برتن ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔
مقریزی کے مطابق 398ھ/1009ء میں اناج کی قیمتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور لوگ روٹیوں پر کتوں کی طرف جھپٹنے لگے۔ چناں چہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہوئی اور انھوں نے اناج کی قلت اور خراب اناج فراہم کیے جانے کے خلاف ہنگامہ کیا۔عوام نے علامت کے طور روٹی ہاتھ میں لے کر حاکم مصر کے پاس شکایت پہنچائی۔
ابن جوزی کی روایت کے مطابق 410ھ/1020ء میں مصری عوام نے ملکی حالات کے خلاف احتجاجی تحریک برپا کر دی اور جس راستے سے فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ عموماً گزرا کرتا تھا، وہاں پر پرانے بوسیدہ کپڑوں سے تیارہ کردہ عورت کا پتلا کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہر بند رقعہ رکھ دیا جس میں خلیفہ کوطرح طرح سے لعن طعن کیا گیا تھا۔خلیفہ کا اس کے پاس گزر ہوا تو اسے اس کے عورت ہونے میں شک نہیں ہوا۔ اس نے سمجھا کہ عورت فریاد لے کر کھڑی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے رقعہ لے لیا۔ کھولا تھا تو اس میں سخت باتیں لکھی تھیں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ دیکھو یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ تو پتلا ہے جسے بوسیدہ کپڑوں سے تیار کیا گیا ہے۔
قید خانوں میں احتجاج
قید خانوں کی تاریک کوٹھریاں بھی مظلومین کو احتجاج کے حق سے نہیں روک پاتی تھیں۔یہ احتجاجات اس خراب صورت حال میں تبدیلی لانے کی غرض سے کیے جاتے تھے جس سے یہ مظلومین جیل کی چہار دیواری کے اندر گزرا کرتے تھے۔ قیدی اپنی تکلیفوں کے سلسلے میں جیل کے ذمے داروں سے فریاد بھی کیا کرتے تھے اور جیل کے عملے کی جانب سے بدمعاملگی اور بدسلوکی کے خلاف احتجاج کرتے تھے۔ یہی احتجاج بڑھ کر مزاحمت اور جیل سے فرار ہونے کی جدوجہد کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا۔
اکثر یہ جدوجہد ناکام ہوجاتی تھی۔ ابن جوزی کی روایت کے مطابق 306ھ/918ء میں [بغداد] کی نئی جیل کے قیدیوں نے ہنگامہ برپا کر دیا اور جیل کی فصیلوں پر چڑھ گئے۔ پھر پولیس نے ان کا مقابلہ کیا۔‘‘ لیکن یہ کوششیں خاص طور سے اس وقت کام یاب ہو جایا کرتی تھیں جب قیدیوں نے شہر کی بدامنی اور شہریوں کی طرف سے احتجاجی تحریک سے فائدہ اٹھا کر جیل سے فرار ہونے کا موقع حاصل کر لیا ہو۔
791ھ/1389ء میں مملوک سلطان ظاہر برقوق (م: 801ھ/1399ء) کے مخالف امراء نے قاہرہ کا محاصرہ کر لیا اور سب کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ سلطان کی شکست طے ہے۔ یہ صورت حال دیکھ کر قاہرہ کے گورنر حسام الدین بن الکورانی کو اپنی جان کا اندیشہ ہوا۔ وہ روپوش ہو گیا۔ عوام میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس موقع پر‘خزانہ شمائل‘)قاہرہ کی جیل) کے قیدیوں نے اپنی بیڑیاں کاٹیں اور جیل کا دروازہ توڑ کر باہر نکل آئے۔ یہی دیلم اور رحبہ کے قیدیوں نے بھی کیا۔
سیاسی سرگرمیوں کے دوران بھی لوگ جیل کے دروازے توڑ دیا کرتے تھے اورمظلوم سیاسی قیدیوں کو آزاد کرالیا کرتے تھے۔ اس قسم کا ایک واقعہ قاضی ابو علی التنّوخی (م: 384ھ/995ء) نے ’نشوار المحاضرہ‘ میں اس طرح نقل کیا ہے کہ 307ھ میں عوام نے شہر المنصور کی جیلیں توڑ دیں اور ان کے اندر موجود قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ لیکن شہر کے آہنی دروازے ابھی تک محفوظ تھے، اس لیے انھیں بند کر دیا گیا اور پولیس نے قیدیوں کا پیچھا کر کے سب گو پکڑ لیا اور کوئی بھی بچ نہیں پایا۔‘‘
احتجاج کے دوران جن مظاہرین کو گرفتار کرکے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، انھیں آزاد کرانے کے لیے بھی جیلوں پر دھاوا بول دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ مجرم نہیں ہوتے تھےکہ انھوں نے عوام کا کو ئی حق مارا ہو، بلکہ حکومت مخالف رائے رکھنے کی وجہ سے گرفتار کر لیے جاتے تھے۔ 843ھ/1439ء میں دمشق کے عوام نے وہاں کے حاکم یعنی مملوک سلطان کے نائب کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی قیام گاہ موسوم بہ ’دارالسعادت‘ پر حملہ بول دیا۔
ابن حجر (بحوالہ اِنباء الغمر) کے مطابق وجہ یہ تھی کہ ایک ملازم نے،جو کہ گورنر کا مقرب تھا گوشت کی ذخیرہ اندوزی کردی جس کی وجہ سے گوشت مہنگا ہو گیا۔ حالات اس حد تک دگرگوں ہو گئے کہ جو گوشت ڈھائی درہم میں فروخت ہوتا تھا وہ آٹھ درہم کا فروخت ہونے لگا۔اس کے خلاف بغاوت ہونے پر نائب نے فوج طلب کی اور ایسے لوگوں کے ایک گروہ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ لیکن باقی لوگوں نے جیل پر حملہ بول کر اس کا دروازہ توڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔
دعا ؤں کی صورت میں احتجاج
ناسازگار حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے پرامن احتجاج کی ایک شکل اجتماعی دعاؤں اور اللہ سے اجتماعی فریاد بھی تھی۔ لوگ سلطان کے ظلم و جور کے خاتمےکےلیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ اسلوب خاص طور سے اس سماج میں اکثر مفید وموثر ثابت ہوا کرتا تھا جہاں دینی اقدار کی چھاپ نظر آتی تھی اور ظالموں اور جابروں کے خلاف آسمانی سزاؤں سے خوف پایا جاتا تھا۔
کبھی یہ دعا بالواسطہ ہوا کرتی تھی۔ یعنی اعلان نامے میں دعائیں لکھ کر کسی بھی صورت ایوان اقتدار تک پہنچائی جاتی تھیں۔ کبھی اجتماعی طور پر مساجد، عوامی میدانوں یا شاہراہوں پر جمع ہو کر دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ لوگ گھروں کے اندر محصور ہو کر یا خصوصی مجالس میں یا بیک وقت دونوں طرح سے بھی حکومت کے خلاف دعائیں کیا کرتے تھے۔
احتجاجی تحریکوں اور عام سیاسی پالیسیوں کے خلاف اظہار نکیر کے لیے اجتمانی دعاؤں کو وسیلہ بنانے کی اولین مثال حضرت عائشہؓ (م: 58ھ/679ء) سے ملتی ہے۔ انھوں نے جب یہ سنا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو انھوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضرت عثمان کے قاتلوں کے لیے بددعا کرنے لگیں۔ لوگ بھی بلند آواز کے ساتھ قاتلین عثمان کے خلاف ان کی بد دعا میں شریک ہو گئے۔‘‘
اس کی ایک مثال ابن مسکَوَیہ (م: 421ھ/1031ء) نے بیان کی ہے کہ عراق پر بویہی وزیر ابوالفضل شیرازی کا دباؤ سخت ہونے لگا تو بغداد کے اندر مساجد و جوامع، کلیسا اور یہودی معبدوں میں کثرت سے اس کے خلاف دعائیں مانگی جانے لگیں۔ ’’اسی طرح ابن الجوزی روایت کرتے ہیں کہ فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ سے اہل مصر تنگ آ کر اس کے پاس ایسی تحریریں بھیجا کرتے تھے جن میں اس کے اور اس کے بزرگوں کے خلاف بددعائیں اور گالیاں لکھی ہوتی تھیں۔
مقریزی نے اپنی کتاب ’’السلوک‘‘ میں لکھا ہے کہ 680ھ/ 1281ء میں تاتاریوں نے دمشق پر حملہ کر دیا۔ دمشق کے تمام باشندگان جامع دمشق میں اکٹھا ہوئے اور گڑگڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی، اس سے فریاد کی اور روتے ہوئے مصحف عثمانی اپنے سروں پر رکھ لیے۔اس کے بعد اللہ سے دشمنوں کے خلاف نصرت و فتح کی دعا مانگتے ہوئے جامع مسجد سے نکل کر شہر کے باہر موجود عیدگاہ کی طرف نکل گئے۔ مورخ ابن ایاس حنفی‘بدائع الزہور‘میں لکھتےہیں کہ مصر میں ماہ رمضان کے ایام میں سلطان نے بہت سے لوگوں کی تنخواہ قطع کر لی۔ چناں چہ اس کے خلاف دعائیں مانگی گئیں۔ اقتدار کے آخری زمانے میں اس کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا۔
منصوبہ بندی کے ساتھ احتجاج
سرکاری موقف کے خلاف احتجاج کے لیے مظاہرین مناسب حالات اور مناسب ترین اسلوب کا انتخاب کیا کرتے تھے تاکہ احتجاج کام یابی کے ساتھ اپنے مطلوبہ اہداف کو حاصل کرسکے۔ اس سلسلے میں اکثر منصوبہ بندی کے تحت ایسے وقت اور مقام کا انتخاب کیا جاتا تھا جب احتجاج کی صدا زیادہ کارگر ثابت ہو۔ احتجاجی سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیےلوگ جمعے کے دن اور جامع مساجد کا انتخاب کیا کرتے تھے۔
اس کی ایک مثال ابن الجوزی نے ’المنتظم‘ میں پیش کی ہے کہ 201ھ/ 816ء میں بغداد کے اندر عباسی خلیفہ ابراہیم بن مہدی کے لیے بیعت کی گئی۔ اس لیے کہ مامون (218ھ/833ء) نےاپنے ولی عہد کا منصب علی بن موسی رضا علوی (م:203ھ/818ء) کو سونپا تو عباسیوں نے مستقبل میں اپنی حکومت کا خطرہ بھانپتے ہوئے اسے مسترد کردیا اور مامون کی بیعت سے نکل کر ابراہیم مہدی اور اس کے بعد اس کے بھائی اسحق بن موسی مہدی سے بیعت کا اعلان کر دیا۔
ایک مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مظاہرین ایسے عوامی مقامات کا انتخاب کرتے تھے جہاں اہل کاروں تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو۔ ابن الجوزی کے مطابق 330ھ میں جامع الرصافہ کے اندر امام خطبہ دے رہا تھا کہ ایک شخص اٹھا اور عباسی خلیفہ المتّقی للہ کے حق میں دعا کرنے لگا۔ ایک عام فرد اٹھا اور بولا کہ ’’تم جھوٹے ہو، خلیفہ متقی نہیں ہے۔‘‘ چناں چہ اس فرد کو گرفتار کرکے سلطان کے پاس لے جایا گیا۔‘‘
قابل توجہ پہلو
تاریخ ہمیں احتجاج کے ایک روشن پہلو سے بھی روبرو کراتی ہے، وہ یہ کہ علمائے مصلحین، یعنی محدثین، صلحاء و فقہائے کرام بھی ظلم وزیادتی کے خلاف پر امن احتجاج میں شامل ہوا کرتے تھے، قطعِ نظر اس سے کہ ظلم کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس شرعی رجحان کا ترجمان ہوا کرتا تھا جو رائے عامہ کوسماجی احتساب (حسبہ) کا یہ حق دیتا ہے کہ وہ ’’قومی نگرانی‘‘ اور مثبت سماجی نظم و ضبط کو رو بہ عمل لاتے ہوئے ظالموں کا ہاتھ پکڑ لے۔
تیونس میں قاضی سحنون بن سعید (م: 240ھ/ 855ء) کم زور عوام پر اعیان سلطنت کے ظلم کو روکنے کی غرض سے قبائل ودیگر طبقات کے معززین و بااثر افراد سے مدد لینے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ان کا علمی مقام و مرتبہ اور عوامی مقبولیت کام آئی۔ قاضی عیاض ’ترتیب المدارک‘ میں کہتے ہیں کہ ’قاضی سحنون کا جو مقام و مرتبہ عوام کے دلوں میں تھا اس کی وجہ سے امیر تیونس محمد بن الاغلب التمیمی (م: 242ھ 856ء) انھیں معزول نہیں کر سکا۔‘‘ چناں چہ قاضی سحنون اپنی وفات تک محکمۂ قضا کی سربراہی کرتے رہے۔
قاضی عیاض نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس سے عوامی قوت و طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قاضی سحنون نے تیونس کے معززین پر مشتمل ایک ہزار مسلح شیوخ کو جمع کیا اور انھیں یہ ذمے داری سونپی کہ ان مسلمان عورتوں کو آزاد کرائیں جنھیں ایک جنگ کے دوران بنو الاغلب (اغالبہ) کے ایک سپہ سالار نے قیدی بنا لیاتھا۔ ان شیوخ نے قاضی سحنون کے حکم پر کمانڈر کے محل کا محاصرہ کیا اور ان عورتوں کو وہاں سے نکال کر سحنون کے پاس لے کر آئے۔
احتجاجی مظاہروں میں علما کی شرکت تاریخ اسلام کی آخری صدیوں تک جاری رہی، جس کی وجہ غالبًا وہ صورت حال تھی جس میں علما کو اقتدار و حکومت کے اثرات اور دباؤ سے آزادی حاصل تھی۔ مثال کے طور پر مصر کے سلسلے میں مورخ الجَبَرْتی نے مصر کے مملوکی اور عثمانی عہد میں عوامی احتجاجات کے تفصیلی واقعات میں اس کا ذکر کیا ہے۔
علمائے ازہر ان احتجاجی مظاہروں کے دوران عوام کے مطالبات کو اپنی حمایت فراہم کیا کرتے تھے، بلکہ تاجروں اور امراء مخالف اہل کاروں کے اتحاد میں شامل ہو کر عوامی احتجاجات کی قیادت کیا کرتے تھے۔ احتجاجی مظاہروں میں ان کی یہ شمولیت عام ہڑتال کی صورت حال پیدا کر دیا کرتی تھی۔ اس دوران بازار بند کر دیے جاتے تھے اور جامع ازہر کے علمی حلقوں میں درس و تدریس کا سلسلہ اس وقت تک کے لیے موقوف ہو جایا کرتا تھاجب تک عوام کے مطالبات پر عمل نہ ہو جاتا ہو اورظلم وزیادتی کرنے والوں کو ایسا کرنے سے روک نہ دیا جاتا ہو۔
الجبرتی کہتے ہیں کہ 1199ھ 1785/ء میں خبر آئی کہ والی جدید مصر (پاشا) اور والی جدہ مصر کی دفاعی سرحد اسکندریہ پہنچنے والے ہیں۔ ان کے اسکندریہ پہنچنے سے چند دن پہلے وہاں اہل شہر اور قلعے کے محافظوں اور فوجی کمانڈروں کے درمیان فتنہ برپا ہو چکا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ فوجی کمانڈر کے کچھ لوگوں نے شہر کے کسی فرد کو قتل کر دیا تھا۔ عوام بھڑک گئے اور انھوں نے کمانڈر کو پکڑ لیا، اسے ذلیل کرنے کے لیے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا گیا۔ اس کی نصف ڈاڑھی بھی صاف کر دی۔ شہر میں اس کا جلوس اس طرح نکالا گیا کہ وہ ننگے سر تھا اور لوگ اس کے سر پر جوتوں اور تھپڑوں سے مار رہے تھے۔‘‘
عوامی محاذ کی تشکیل
اسی ضمن میں ایک واقعہ 1209ھ 1794/ء کا ہے کہ شہر بلبیس کے ایک گاؤں کے لوگ شیخ الازہر عبداللہ الشرقاوی( م: 1227ھ 1812ء) کے پاس آئے اور بعض مملوکی امراء کی شکایت کی جو ان پر ظلم کر رہے۔ اس کے لیے انھوں نے شیخ سے مدد چاہی۔ شیخ غضب ناک ہوگئے اور جامعہ ازہر پہنچ کر علما و مشایخ کو جمع کیا۔ جامعہ ازہر میں قفل ڈالا اور لوگوں کو حکم دیا کہ بازاروں اور دکانوں کو بند کر دیں۔‘‘
یہ مجمع جامعہ ازہر کے قریب ایک مقام پر جمع ہو ا۔ وہاں سے کثیر تعداد میں خلق خدا ان کے ساتھ شامل ہو کر اس طرف چل پڑی جہاں شہر کے منتظمین اور اہل کاروں کے دفاتر تھے۔ وہاں لوگوں نے تقریریں کیں اور کہا کہ ’’ہم عدل چاہتے ہیں، ظلم وانصاف کا خاتمہ اور شریعت کا قیام چاہتے ہیں۔۔۔‘‘ احتجاج کا اختتام اس طرح ہوا کہ اہل کار اپنی حرکت سے تائب ہوئے اور علما نے جو شرطیں رکھی تھیں ان کی پابندی کا وعدہ کیا۔ آخر میں اس بات پر صلح ہوئی کہ حکومتی کارندے لوگوں کے اموال پر دست درازی سے باز رہیں گے۔‘‘
ایسے احتجاجات بھی ہوئے جن میں حکومتی اہل کاروں کے ظلم وستم کے ازالے کی غرض سے علما اور عوام نے مل کر جدوجہد کی۔ ایسے ایک واقعے کی اطلاع الجَبَرتی نے دی ہے کہ 1200ھ/ 1785ء میں جب بعض فوجیوں اور امراء نے قاہرہ کے محلوں میں لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار مچائی تو عوام الناس حرکت میں آ گئے۔ سب لوگ جامعہ ازہر کے پاس جمع ہوئے۔ انھوں نے طبلے اور ڈھول لے رکھے تھے۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے ہوئے تھے۔ اسی حال میں وہ شیخ احمد الدَّردیر کے پاس آئے۔ شیخ الدردیر نے ان کی باتوں سے اتفاق کرتےہوئے ان کا حوصلہ بڑھایا۔
شیخ الدردیر نےاپنی گفتگو سے مظاہرین کا غصہ قابو میں کیا پھر انھیں خطاب کرکے فرمایا: ’’کل ہم اطراف کے محلوں، بولاق اور قدیم مصر کے لوگوں کو جمع کریں گے۔ میں تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا اور ہم سب ان کے گھروں کو اسی طرح لوٹیں گے جس طرح انھوں نے ہمارے گھروں کو لوٹا ہے، اور یا تو شہید کی موت مر جائیں گے یا اللہ ان کے خلاف ہماری مدد فرمائے گا۔‘‘ اہل کاروں کو خطرے کا اندازہ ہوا تو ’’شیخ الدردیر کے پاس آئے اور حالات بگڑ جانے کا اندیشہ ظاہر کیا۔ انھوں نے شیخ سے کہا: ’’ہمیں آپ لوٹے جانے والے سامان کی فہرست بنا کر دے دیں۔ وہ سامان جہاں بھی ہوگا ہم آپ کو لا کر دیں گے۔‘‘
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الدردیر محض فقیہ نہیں تھے بلکہ عوامی قائد بھی تھے۔ اس سے یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہوتا ہےکہ عوام الناس میں علما کی قیادت کا سکہ محض ان کی علمی شخصیت وحیثیت کی وجہ سے نہیں جما ہوا تھا، بلکہ اس لیے بھی تھا کہ وہ عوام کے درمیان سے ظلم کو رفع کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے تھے اور عدل و انصاف کے مطالبے کو لے کر جو احتجاجی مظاہرے ہوتے تھے ان میں آگے آگے رہتے تھے۔
کاروباری انجمنوں کا کردار
مختلف سماجی گروہوں اور طبقات کی طرزپرپیشہ ورانہ انجمنوں نے بھی حکومتی کارندوں کے ظلم و جو رکے خلاف مزاحمت میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر‘ترکی اناضول انجمن‘ کا ذکر ابن بطوطہ نے کیا ہے اور انجمن کے متعلقین کے بارے میں اپنے سفرنامے میں یوں لکھا ہے: ’’اجنبیوں اور غیر ملکیوں کا خیال رکھنے میں ان سے اچھی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ لوگ اجنبیوں اور مسافروں کو کھانا پیش کرنے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں، ظالم کا ہاتھ پکڑنے، پولیس یا جس نے بھی انھیں تکلیف پہنچائی ہو اسے قتل تک کر ڈالنے میں بڑے چابک دست ہیں۔‘‘
بعض کاروباریوں نے اپنے خلاف ہونے والے مظالم کے خلاف مزاحمت کا ذریعہ کاروباری ہڑتال کو بنایا۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ کاروباری انجمنوں میں ایک نظم پایا جاتا تھا جو ان کے موقف کو متحد رکھتا تھا تاکہ اپنے مطالبے پورے کرانا آسان ہو۔ علامہ راغب اصفہانی (م: 502ھ 1108/ء) ’محاضرات الادباء‘ میں لکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایران کے شہر قُم کے حجام ناراض ہو گئے۔ وہ سب یکجا ہو کر شہر سے باہر نکل گئے۔ اہل شہر کے بال لمبے ہو گئے تو مجبور ہو کر ان کے پاس گئے۔ ان کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ انھیں اذیت نہیں پہنچائیں گے اور نہ کسی تکلیف دہ اور ہتک آمیزلقب سے پکاریں گے۔ چناں چہ انھوں نے شہر واپس آکر اپنی دکانیں سنبھال لیں۔
بلا تفریق مذہب احتجاج
باوجود اس کے کہ مختلف محرکات و اسباب کے تحت اور مختلف نوعیت کے احتجاجی مظاہروں میں شرکا کی غالب اکثریت مسلم طبقے سے ہی تعلق رکھتی تھی، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف مسلمان ہی ان میں شریک ہوا کرتے تھے، بلکہ سرکاری ظلم و جبر کا مقابلہ کرنے اور امن و استحکام کی بحالی کے سلسلے میں اکثر و بیش تر ان کے معاون و مددگار دوسرے مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والے برادران وطن ہوا کرتے تھے۔ اس طرح وہ بقائے باہمی میں مذہب کے ایجابی کردار کی اچھی مثال پیش کرتے تھے۔
شاید اس کی حیرت انگیز مثال وہ واقعہ ہے جو 363ھ 974/ء میں دمشق کے اندر پیش آیا تھا۔ فاطمی فوجی کمانڈر ابومحمود ابراہیم بن جعفر الکُتّامی شہر کے اندر داخل ہوا تو دمشق کے مختلف محلوں میں امن کی صورت حال بگڑ گئی۔ لوگوں نے امن و استحکام کے فقدان کے خلاف احتجاج کیا۔ ہر مذہبی طبقہ اپنی مقدس کتاب لے کر اس میں شریک ہوا اور جامع اموی میں جمع ہو کر ہر مذہبی طبقے نے امن کی بحالی کے لیے دعا کی۔
المقریزی (م: 845ھ/ 1441ء نے ’اتّعاظ الحُنفا‘ میں ذکر کیا ہے کہ جب حالات دگر گوں ہو گئے اور آزمائش سخت ہوگئی تو اہل دمشق نے ’مشایخ شہر‘ کی قیادت میں جلوس نکالا جو فساد کی مذمت اور امن کی بحالی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس جلوس میں مسلمان اپنے مصحف کے ساتھ، عیسائی انجیل کےساتھ اور یہودی تورات کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ سب لوگ جامع اموی میں جمع ہو ئے اور سب نے گڑگڑا کر دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد شہر کا چکر اس طرح لگایا کہ سب نے سروں پر مذہبی کتابیں رکھ رکھی ہوئی تھیں۔‘‘
مصر کے فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے عوام پر ظلم کی انتہا کر دی تو 395ھ/ 1006ء میں اس کے کُتّامی حلیفوں نے اکٹھا ہو کر اس سے فریاد کی، اسی طرح تمام اہل کار، کارکنان،فوجیوں، تاجروں اوریہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اکٹھا ہو کر اس سے معافی کی درخواست کی۔ المقریزی نے مزید لکھا ہے کہ اس نے معافی نامہ جاری کیا جس کی ایک نقل مسلمانوں کو، ایک عیسائیوں اور ایک یہودیوں کو فراہم کی گئی۔
الگ الگ نتائج
احتجاجی مظاہروں سے تعلق رکھنے والے مختلف نوعیت اور پس منظر کے یہ واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اکثر یہ احتجاج پرامن انداز سے شروع ہو کر پرامن حالت میں ختم ہوتے تھے اور مظاہرین کی طرف سے کیے جانے والے مطالبات کلی یا جزئی طور پر پورے کر دیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی احتجاج پر تشدد تحریک کی شکل بھی اختیار کر لیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں عمومی بحران کی شکل پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ حکام کا تختہ تک پلٹ دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات احتجاج تو پرامن طور پر شروع ہوتا تھا لیکن حکومت کی جانب سے تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایسی صورت میں یا تو احتجاج کی آگ بجھ جاتی تھی، یا صورت حال سنگین ہو کر خود حکم راں کے قابو سے بھی باہر ہو جاتی تھی۔
اکثر جب حکومت و اقتدار احتجاج کاروں کے مطالبات تسلیم کر لیتی تھی تو احتجاج نتیجہ خیز ثابت ہوتا تھا۔ مثال کے طورپر امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ 194ھ/ 810ء میں اہل حمص نے اپنے نائب کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تو عباسی خلیفہ الامین نے اسے معزول کر دیا اور عبداللہ بن سعید الحَرَشی کو نیا گورنر مقرر کر دیا۔اس شخص نے ان کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، لیکن عوام اس کے سامنے جھکے نہیں، اور ابن کثیر کے الفاظ میں ’’عوام دوبارہ بپھر گئے تو اس نے ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کی گردنیں مار دیں۔‘‘
مملوکی دور کے مصر کے بارے میں امام ابن حجر ’انباء الغُمر‘ میں بتاتے ہیں کہ 797ھ/ 1395ء میں بعض لوگوں نے قاضی شہاب الدین الباعونی (م:816ھ 1413ء) کے سلسلے میں شکایت کی تو سلطان نے انھیں معزول کرکے ان کی جگہ علاء الدین بن ابو البقاء (809ھ 1406ء) کو قاضی مقرر کر دیا۔
عثمانی دور کے شہر حلب میں یہ ہوا کہ 1184ھ/ 1772ء میں حکومت پر خالص دینی بنیادوں پر دباؤ بنانے کے لیے عوام نے تحریک چلائی اور حکومت کو ان کے مطالبات تسلیم کرنے پڑے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ’’علما اور عوام کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو کر شرعی عدالت کے اندر داخل ہو گیا اور عدالت سے بعض بدعتوں اور دین میں انحراف کی علامت والے کاموں کو بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا گیا۔‘‘ (نہر الذہب فی تاریخ حلب از مورخ کامل الغزی)
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ انتظامیہ مطالبات کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے ٹالنےکی کوشش کرتی تھی، لیکن بڑھتے ہوئے احتجاجی دباؤ کے سامنے اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں رہ جاتی تھی۔ 799ھ/ 1379ء میں بہاء الدین ابن البرجی کےمحتسب (ناظم حسبہ) مقرر ہوتے ہی اتفاق سے مہنگائی بڑھ گئی۔ لوگوں نے اسے بدشگونی سمجھا۔ ابھی اسے اپنے عہدے پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عوام نے سلطان کے سامنے اس کے سلسلے میں اپنی بے اطمینانی کا اظہار کیا۔ لیکن سلطان نے ضد میں آکر اسے خلعت سے نوازدیا۔ علامہ ابن حجر کے مطابق عوام نے ابن البرجی پر سنگ باری کی اور خود ہی اسے عہدے سے معزول کر دیا۔
کبھی کبھی حکومت بے مہار سختی اور ظلم کے ذریعے احتجاج کو روکنے کی کوشش کرتی تھی۔ مصر کے فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو اپنے خلاف بعض احتجاجی طریقوں پر غصہ آیا تو اس نے فوجی کمانڈروں اور قبائلی سرداروں کو بلوایا۔ سب لوگ آ گئے تو انھیں مصر (فسطاط) روانہ ہونے کا حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دیں، لوٹ مار مچائیں اور وہاں کا جو آدمی ہاتھ آئے اسے قتل کر دیں۔ یہ لوگ اس طرف روانہ ہو گئے۔ مصریوں کو اس کی خبر ہوئی تو اپنے دفاع کے لیے جی جان سے جنگ لڑی۔ [سرکاری] غلاموں اور عوام کے درمیان یہ جنگ تین دن تک جاری رہی۔
کبھی نظام حکومت احتجاج کاروں کا مقابلہ اس طرح بھی کرتا تھا کہ ان پر تابڑتوڑ حملے کرکے جیل کی کال کاٹھریوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ مملوکی سلطان فَرَج بن برقوق (م: 815ھ 1412ء) نے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی کرنسی پالیسی اختیار کی تو [مصر کی] دکانیں بند کر دی گئیں۔ سلطان کو غصہ آگیا اور اس نے اپنے ہنگامہ برپا کرنے والے غلام سپاہیوں کو عوام پر تلوار چلانے کا حکم دے دیا۔ امراء نے عوام کی طرف داری کی تو ان کی جماعت کو گرفتار کرکے کوڑوں سے مارا گیا۔ کرنسی کے معاملے میں ہی ایک آدمی کو قتل کر کےسولی پرلٹکا دیا گیا۔( انباء الغمر از علامہ ابن حجر)
مورخ الجبرتی اپنی کتاب ’عجائب الآثار‘ میں کہتا ہےکہ 1191ھ/ 1777ء میں جامعہ ازہر کے پڑوس میں آباد مراکشی گروہ میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ انھیں ظلم کا نشانہ بنایا گیاتھا۔ ان مظلومین نے شیخ احمد الدردیر (مالکی شیخ) کو مطلع کیا۔ انھوں نے یوسف بیگ کے نام ایک خط لکھا جس میں اہل علم کو ظلم کا نشانہ بنانے اور شرعی حکم کی مخالفت کی بات کہی گئی تھی۔ ۔۔۔ جب یہ لوگ خط لے کر یوسف بیگ کے پاس پہنچے اور اسے میمورنڈم پیش کیا تو اس نے انھیں برا بھلا کہا اور گرفتار کرکے قید خانے میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔
اس کی خبر شیخ الدردیر تک پہنچی تو انھوں نے محسوس کیا کہ حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے علمائے کرام پر مشتمل ایک وسیع احتجاجی محاذ تشکیل دینا ضروری ہو گیا ہے۔ انھوں نے جامعہ ازہر کے تمام افراد کو مدعو کیا۔ اگلی صبح سب جمع ہوئے اور درس و تدریس، اذان و نماز سب کو معطل کر دیا گیا۔ جامعہ ازہر کے دروازوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ علما و مشایخ ’قبلہ قدیم‘ پر بیٹھ گئے اور بچے مناروں پر چڑھ کر بلند آواز سے چیخ چیخ کر امراء کے خلاف بددعائیں کرنے لگے۔ آس پاس کے بازار بھی بند کر دیے گئے۔ قاہرہ کے عین وسط میں زندگی کے مکمل طور پر مفلوج ہوجانے کی وجہ سےمملوکی امراء کو حالات کی خطرناکی کا اندازہ ہو گیا۔ چناں چہ یوسف بیگ کو حکم بھیجا تو اس نے قیدیوں کو آزاد کیا۔
بہرحال سول مظاہرے تمام کے تمام محض حکومت، اس کی کارگزاریوں اور پالیسیوں کی مذمت کے لیے ہی نہیں منعقد کیے جاتے تھے، بلکہ حکم راں اگر عدل پسندہوتا اور اس کا کردار اورپالیسی لوگوں کو پسند آتی تو اس کی تائید وحمایت کے لیے بھی لوگ مظاہرے کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عباسی خلیفہ مہتدی باللہ (م: 256ھ/ 870ء) کے زمانے میں اس قسم کا مظاہرہ ہوا تھا۔ اس عباسی خلیفہ کو اموی خلیفۂ راشد عمر بن عبدالعزیز (م: 101ھ/ 720ء) کی نظیر بتایا جاتا تھا۔
ہوا یوں کہ جب ترک افواج نے خلیفہ مہتدی باللہ کو معزول کرنا چاہا تو عوام نے خلیفہ کی حمایت و تائید میں فوج کے مقابل بغاوت کا اعلان کر دیا۔ عوام کی بھیڑ جمع ہو گئی اور پرچے لکھ لکھ کر راستوں اور مسجدو ں میں پھینک دیے گئے جن پر لکھا ہوا تھا: ’’اے مسلمانو! اپنے عادل و پسندیدہ خلیفہ کے لیے اللہ سے دعا کرو جو کہ عمر بن عبد العزیز کے مشابہ ہے۔ خلیفہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے دشمنوں کے خلاف اس کی مدد کرے، ظالموں کے شر سے اسے محفوظ رکھے، اور اس کے باقی رہنے سے اس پر بھی اور امت پر بھی نعمتیں تمام ہوں۔ ترکوں نے اسے اپنی مرضی سے معزول ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کئی دنوں سے عذاب میں مبتلا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔‘‘ (تاریخ الکامل، از ابن الاثیر)
نیک و پاک باز عباسی وزیر ظہیرالدین الروذراوری (م: 488ھ/ 1095ء) کے حالات زندگی میں ابن خلکان نے ’وفیات الاعیان‘ میں لکھا ہے کہ وزیر عمید الدولہ ابو منصور ابن جہیر کی معزولی کے بعد اسے خلیفہ متقدی بامر اللہ (م: 487ھ/ 1094ء)کا وزیر مقرر کیا گیا۔ ظہیر الدین اپنی معزولی کے بعد جمعہ کے دن پیدل چل کر جامع مسجد آیا۔ عوام اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے اور اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔اس وجہ سے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔
ایسا لگتا ہے کہ حکومت عوام کے اس محبوب وزیر کے عوامی اثرات سے خوف زدہ ہو گئی تھی، کیوں کہ اس کے سامنے رہنے سے لوگوں کو اس کے زمانے کے خوش حال دن یاد آتے رہتے۔ اس لیے اس پر نظر بندی عائد کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم کے سربراہوں، مثلاً علما و اعیان کے غضب و غصے کی ایک حد ہوتی ہےاور اسے قابو میں کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن عوام کے غیظ و غضب کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا۔ احتجاجات کی طویل داستان جو ہم نے اس مضمون میں پیش کی ہے، یہی بتاتی ہے۔
(بشکریہ الجزیرہ ویب سائٹ)