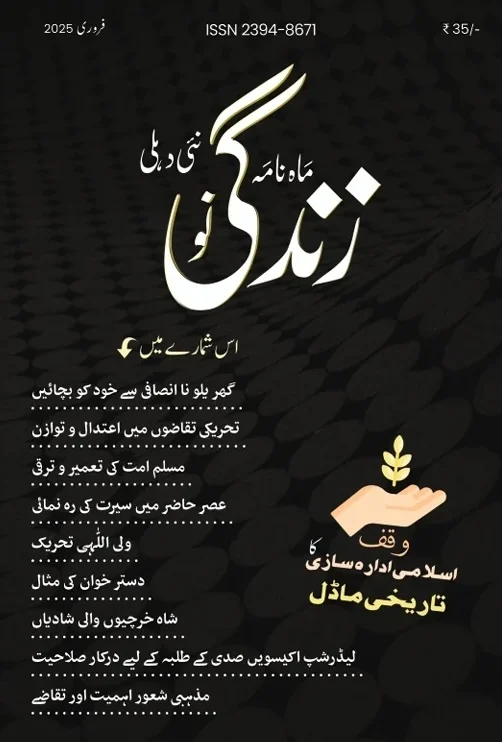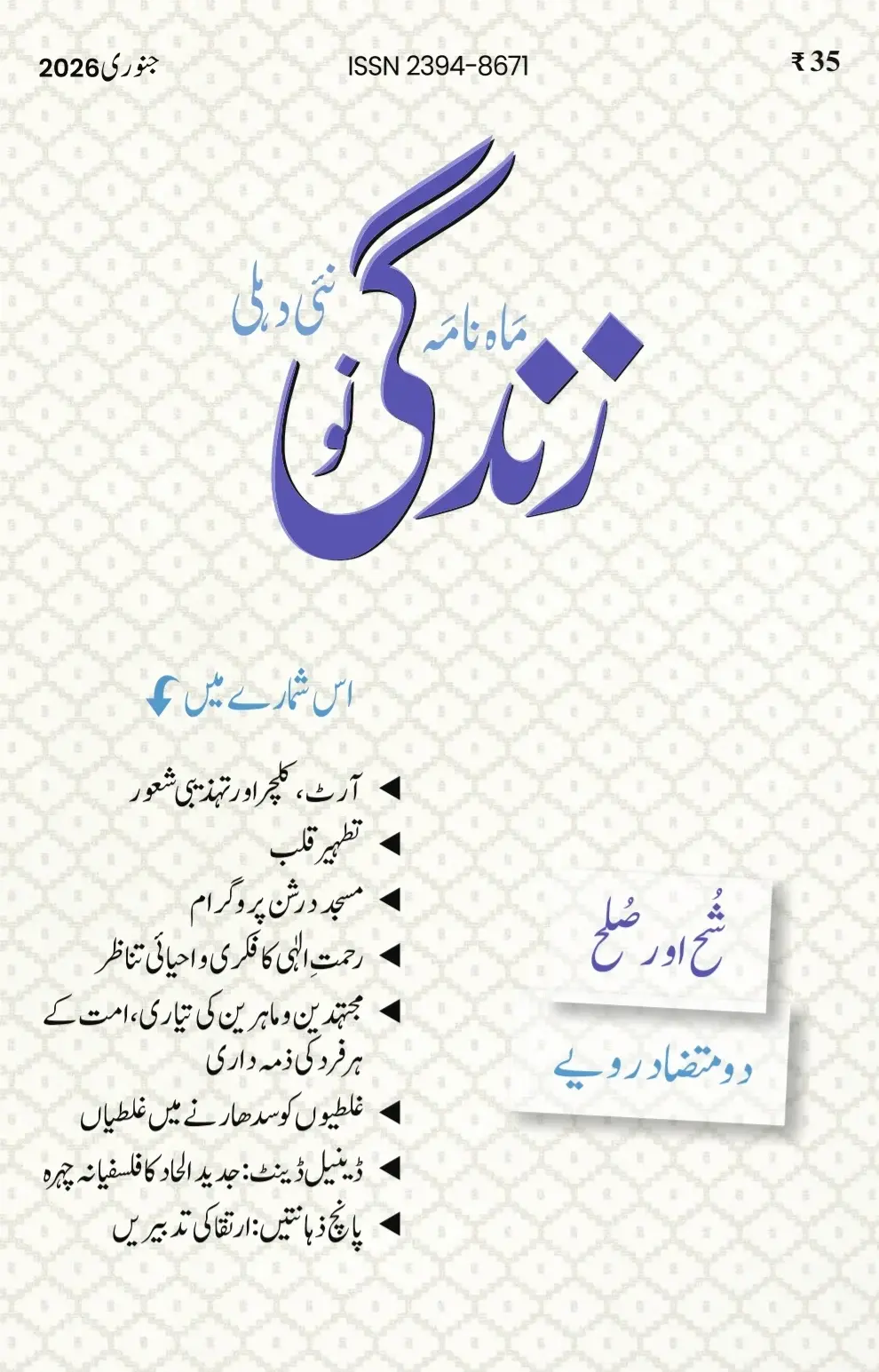برصغیر میں اسلام کے مجدد
شاہ ولی اللہ دہلویؒ کو اس صدی کا اسلامی مجدد قرار دیا جاتا ہے۔اس سے مسلم تشخص اور بیانیے کی تشکیل میں شاہ ولی اللہ کے بلند قد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجدد نبی نہیں ہوتا لیکن اپنے مزاج میں مزاج نبوت سے بہت قریب ہوتا ہے۔ نہایت صاف دماغ، حقیقت رس نظر، ہر قسم کی کجی سے پاک، بالکل سیدھا ذہن، افراط و تفریط سے بچ کر توسط و اعتدال کی سیدھی راہ دیکھنے اور اعتدال و توازن قائم رکھنے کی خاص قابلیت، اپنے ماحول اور صدیوں کے جمے اور رچے ہوئے تعصبات سے آزاد ہوکر سوچنے کی قوت، زمانے کی بگڑی ہوئی رفتار سے لڑنے کی طاقت و جرأت، قیادت و رہ نمائی کی پیدائشی صلاحیت، اجتہاد اور تعمیر نو کی غیر معمولی اہلیت اور ان سب باتوں کے ساتھ اسلام کے بارے میں مکمل شرح صدر، جس میں یہ بات شامل ہے کہ وہ نقطہ نظر اور فہم و شعور میں پورا مسلمان ہوتا ہے، باریک سے باریک جزئیات تک میں اسلام اور جاہلیت کے درمیان تمیز رکھتا ہے اور مدت ہائے دراز کی الجھنوں میں سے امر حق کو ڈھونڈ کر الگ نکال لاتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن کے بغیر کوئی شخص مجدد نہیں ہوسکتا اور یہ وہ چیزیں ہیں جوکمال درجے میں نبی میں ہوتی ہیں۔ [1] درحقیقت شاہ ولی اللہ کا شمار تاریخ انسانی کے ان نمایاں ترین رہ نماؤں میں ہوتا ہے جنھوں نے اپنی علمی قوتوں کے بل بوتے الجھے ہوئے خیالات اور افکار کے جنگل میں سے علم و عمل کی ایک واضح صراط مستقیم اختیار کی۔جب آپ ان کی کتابوں کی ورق گرانی کرتے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں ایسی جگہ لکھی گئی ہیں جہاں عیش و عشرت، خود پسندی، قتل و غارت گری اور جبر و انتشار کا دور دورہ تھا۔ [2]
برصغیر میں جتنے بھی دینی تعلیمی ادارے ہیں بیشتر بالواسطہ یا بلاواسطہ شاہ ولی اللہ سے اپنی وجودی نسبت رکھتے ہیں۔ وہ ’علما‘ اور ’مشائخ‘ کے لیے بہت زیادہ حوصلے اور رہ نمائی کا ذریعہ ہیں۔ انھی کے دریائے فیض سے علامہ شبلی نعمانی، محمد اقبال، سید ابوالاعلیٰ مودودی، سیدابو الحسن علی ندوی اور ان جیسی دیگر مردم ساز شخصیات سیراب ہوئی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اس سنہری سلسلے کی اہم شخصیات میں سے ایک سید احمد شہید تھے۔
اس لحاظ سے اٹھارہویں اور انیسویں صدیاں بڑی زرخیز گزری ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران برصغیر میں مختلف احیا پسند تحریکوں نے جنم لیا ہے، چاہے ہندو احیا کی تحریکیں ہوں جیسے بھکتی تحریک، رام کرشنا مشن، برہمو سماج وغیرہ یا اسلامی نشاة ثانیہ کی کوششیں۔ سوال یہ ہے کہ برصغیر میں برطانوی نوآبادیاتی نظام کے دوران ہندو مسلم نشاة ثانیہ کی تحریکیں کیوں برپا ہوئیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے غیر استعماری عدسہ (decoloniality lens) سے کام لیتے ہیں۔ دراصل یہ تحریکیں یوروپ کو مرکز قوت قرار دینے والے نظریے (Eurocentrism) اور علم و معرفت اور بشری وجود پر نوآبادیاتی تسلط کی مزاحمت کا ردعمل تھیں۔ ان تحریکوں نے یوروپی ثقافت کی بالادستی کی سوچ کو چیلنج کیا۔ ان کا مقصد مغربی جدیدیت کے تسلط اور نوآبادیاتی استعمار کا خاتمہ تھا۔ چناں چہ شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید کی تحریکیں اسلام کی داخلی اصلاح نو کی داعی تھیں، جس طرح دوسری طرف ہندو مذہبی یا تہذیبی محاذ پر دیگر تحریکیں نبرد آزما تھیں۔
چوں کہ یہ تحریک برطانوی تسلط اور نوآبادیاتی حکم رانی کو راست چیلنج کررہی تھی اس لیے یہ تحریک برطانوی حکم رانوں کے گلے میں کانٹا بن کر چبھ رہی تھی۔ انھوں نے اسے ’’وہابی تحریک‘‘ کا نام دیا تھا۔ اس نام کے پیچھے ان کا مقصد عوام کو اس تحریک سے متنفر کرنا اور انتشار پیدا کرنا تھا کیوں کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے پیروکار عام طور پر مسلم دنیا کی جانب سے احتقار کا شکار تھے۔ بیشتر یورپی مورخین اور خاص طور پر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر (W.W.Hunter) نے اپنی کتاب (Indian Musalmans) میں سید احمد کی اصلاحی تحریک کو ’’وہابی تحریک‘‘ سے تعبیر کرتے ہوئے وہابیت کو برطانوی سرکار کے خلاف بغاوت کے مترادف قرار دیا ہے۔ [3]
جے سائی دیپک نے اپنی کتاب[4] (India, Bharat and Pakistan: The Constitutional Journey of a Sandwiched Civilisation) میں ہندوستان میں اس تحریک کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ لیکن ان کا بیانیہ غیر استعماریت کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اپنے تقابل میں ’بین ثقافتی‘ [5] اور ’تکثیریت‘ [6]کی اصطلاحات کا استعمال نہیں کرتے. اس کے بجائے وہ اسے ’ثقافتی جنگوں‘ اور ’تہذیبوں کے تصادم‘ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، جو غیر نوآبادیاتی (decoloniality) اصول سے بالکل متصادم ہے۔ وہ تاریخ کا ازسرنو مطالعہ کرتے ہیں، استعمار کے خاتمہ کے لیے قدیم ہندو قوم پرستی کو نمونہ بناکر ایک نیا عنوان قائم کرتے ہوئے، اسے ہندو تہذیب کے احیائے جدید کا نام دیتے ہیں اور دوسری طرف اسلامی نشاة ثانیہ کی تحریکوں اور عام طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو جدید ’دہشت گردی کی جنگ‘ کا عنوان دیتے ہیں۔
ہم شاہ ولی اللہ اورسر سید احمد کی تحریک نشاة ثانیہ کے لیے ’’ولی اللّٰہی تحریک‘‘ کے نام کو ترجیح دیتے ہیں، جسے عام طور پر برطانوی مؤرخین اور ہندو قوم پرستانہ مؤرخین نے ’’وہابی تحریک‘‘ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ ولی اللّٰہی تحریک اور عام طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں جے سائی دیپک کی کتاب کے بنیادی نکات اس طرح ہیں:
مسلمان ہندوستانی معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ گنگا جمنی تہذیب جیسی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی تھے جنھوں نے مسلمانوں کو ہندوستانی معاشرے میں ضم نہ ہونے کی تلقین کی۔ ’’دہلوی کی تعلیمات میں سے ایک اہم تلقین برصغیر کے مسلمانوں کو ہندوستانی معاشرے سے الگ تھلگ رہنے کی تھی، کیوں کہ ان کے بقول ہندوؤں کے ساتھ ان کا تعلق ان کے پاکیزہ اسلامی عقائد کو آلودہ کرنے کا باعث ہوگا۔‘‘ (13.p)
مسلمان اپنی علاحدگی اور بیگانگی برقرار رکھنے کے لیے فارسی اور عربی جیسی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ’’اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد اور ہندو پڑوسیوں کے مشرکانہ عقائد اور بت پرستی سے متاثر ہونے سے پہلے قرآن سیکھ لیں، دہلوی نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا‘‘ ۔ (p.13)
وہابیت مشرق وسطیٰ میں برپا ہوئی تحریک ہے۔ مسلمان قرآن و حدیث اور عرب مسلمانوں کی اتباع کرتے ہیں کیوں کہ وہ نبی ﷺ کے راست طور پر پیروکار تھے۔ مصنف نے صاف طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستانی مسلمان ہندوستانی نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ مصنف کا موضوع عقیدے سے ہٹ کر شہریت کی طرف مڑجاتا ہے۔ ’’انھوں (شاہ ولی اللہ دہلوی) نے ضروری قرار دیا کہ برصغیر کے مسلمان ابتدائی عرب مسلمانوں کے رسوم و رواج کی پیروی کریں کیوں کہ وہ پیغمبر ﷺ کے راست طور پر پیروکار تھے۔‘‘ (p. 13) …….. ’’میرا خاص مقصد مشرق وسطیٰ کی استعمار کی طویل تاریخ (علاقائی اور وقتی دونوں) کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے جس کی عکاسی وہابی تحریک، اس کے طریقہ کار اور اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ یہ ذہنیت اب بھی پروان چڑھ رہی ہے‘‘ (p.19) …….. یہ بات واضح ہے کہ صرف بھارت میں پیدائش ہی کسی کو بھارتی نہیں بناتی، کیوں کہ بھارتی ہونے کا شعور نسل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب تک ذہنی شعور ہندی عنصر کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، یہ اجنبی ہی رہتا ہے، باوجود اس کے کہ پیدائشی طور پر بھارتی ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں۔‘‘ (p.13)
غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مصنف اپنا نفس موضوع عقیدے سے شہریت کی طرف موڑلیتا ہے چوں کہ مسلمان اسلامی عقیدے کی پیروی کرتے ہیں۔ مصنف کی جانب سے ہندوستان کو ایک ’’واحد ہندو ثقافتی شناخت‘‘ (Singular Hindu Cultural Identity) یا ’’ثقافتی بہم آمیزی‘‘ (Cultural Homogenisation) کے طور پر بیان کرنا غیر استعماری نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ تہذیبی پہلو سے وحدت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ’’مقامی یا بیرونی‘‘ جیسی تنگ نظر سے دیکھنے کے بجائے وسیع تر سماجی سیاسی حرکیات کے کینوس میں دیکھا جائے۔ اس طرح کی تصویر کشی عدم اعتماد اور بیگانگی کو جنم دیتی ہے۔
مصنف نے حالیہ ’’دہشت گردی کی جنگ‘‘ کے مروجہ بیانیے کو وہابی تحریک اور اس میں غیر نوآبادیاتی اور فرقہ واریت کے تصور سے متوازی طور پر جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے اس موقف کو اس طرح تحریر کرتے ہیں: ’’قارئین نوٹ کریں کہ یہ اس پس منظر میں ہے کہ صوبہ سرحد میں بالاکوٹ، جو کہ موجودہ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخواہ کے نام سے جانا جاتا ہے، بھارت اور وسیع پیمانے پر برصغیر کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، اپنے اہم کردار کی بنا پر جو وہ جہادیوں کو راغب کرنے اور انھیں تربیت دے کر ادا کررہا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہ حوالہ سرجیکل اسٹرائیک کی تاریخی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے جو 2019 میں پلوامہ خودکش بم دھماکے کے جواب میں ہندوستانی فضائیہ نے بالاکوٹ میں کیا تھا۔ موجودہ دور میں بعض واقعات کو کسی سوچ وفکر کے تسلسل کے طور پر شناخت کرنے کے بجائے علاحدہ طور پر دیکھنے کے رجحان کے پیش نظر اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کی نشان دہی کرنے کی ضرورت ہے جس کے بیج سید احمد کی جماعت نے 1800 کی دہائی میں بوئے تھے‘‘ (p. 25)۔
اس بیانیے کو پڑھنے کے بعد کسی کے ذہن میں کچھ منطقی سوالات پیدا ہوسکتے ہیں: اس بیانیے کو کس نے تیار کیا؟ W.W. Hunter جیسے برطانوی مورخین کا اس میں کیا رول ہے؟ جنھوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی اور جنھیں برطانوی راج کا دشمن اور باغی کہا گیا تھا، انھیں آج دہشت گرد کیوں کہا جا رہا ہے؟ محب وطن کیوں نہیں؟ مجاہد آزادی کیوں نہیں؟
نوآبادیاتی دور میں ہندومت سمیت تمام مذاہب پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ان کی اصلاح نو کی گئی۔ لیکن امت مسلمہ کی داخلی اصلاح کی داعی ولی اللّٰہی تحریک کو وہ مقام کیوں نہیں دیا گیا؟ انھیں تکثیری اقدار (plural values) اور ہندوؤں کا دشمن کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے علمی حوالوں کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ جئے سائی دیبپک اور انھی کی طرح کے مؤرخین کی پیش کردہ ادھوری سچائیوں اور کذب بیانیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم انھی حوالوں سے استفادہ کریں گے جن کو انھوں نے استعمال کیا ہے۔ اس میں سرفہرست برطانوی مورخ W. W. Hunter اور اس کی انتہا پسندانہ انداز میں لکھی گئی تاریخ کے علاوہ قیام الدین احمد اور دیگر مؤرخین شامل ہیں۔
ہندو، سکھ، اور ولی اللّٰہی تحریک
ولی اللّٰہی تحریک کا اثر اٹھارہویں اور انیسویں، دو صدیوں کو محیط رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اٹھارویں صدی میں مسلم معاشرے کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش شروع کی۔ انیسویں صدی میں اسی مشن پر کام کررہے ان کے شاگردوں اور تلامذہ نے ان کے کام کو آگے بڑھایا۔ برطانوی جبر کے خلاف اس مزاحمتی تحریک کا خاتمہ 1831 میں بالاکوٹ کی جنگ میں ہوا۔ اگرچہ سید احمد شہید یہ جنگ ہار گئے لیکن یہ جدوجہد برصغیر کی تاریخ میں مزاحمت اور قربانی کی علامت بنی ہوئی ہے۔ یہ جنگ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف لڑی گئی لیکن کیا سید احمد شہید کی مزاحمتی تحریک سکھوں کے خلاف تھی یا انگریزوں کے خلاف؟ کیا یہ ہندو مخالف جنگ تھی؟ اس سوال کا جواب قیام الدین احمد نے اپنی کتاب ہی میں درج ذیل انداز میں دیا ہے۔
اس تحریک کے بارے میں ایک غلط فہمی جو عام ہوئی اور انگریزی اور کچھ حد تک اردو تحریروں میں بھی شائع ہوئی، یہ تھی کہ اس جنگ کا رخ سکھوں کے خلاف تھا۔ سید احمد نے نظریاتی، تکنیکی اور اسٹریٹجک حکمت عملی کے مدنظر شمال مغربی سرحدی قبائلی علاقے میں اپنے آپریشن کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ نتیجے کے طور پر دیگر چیزوں کے علاوہ، سکھ دربار کی افواج کے ساتھ تصادم کا باعث بنا جن کے علاقے سید احمد کے مرکز اور برطانوی ہندوستان کے درمیان واقع تھے۔[7] چناں چہ برطانوی حکام نے سید احمد اور ان کے پیروکاروں کو ’’وہابی‘‘ قرار دیتے ہوئے ان کو کم زور ترین حالت میں بھی ہندوستان میں اپنی حکم رانی کے استحکام کے لیے خطرہ سمجھا اور 1845 میں پنجاب کے انضمام تک مسلسل فوجی حملوں کا نشانہ بنایا۔ ان سب باتوں کے باوجود اس موقف پر ڈٹے رہنا کہ وہابی تحریک کا رخ برطانوی حکومت کے بجائے سکھوں کے خلاف تھا، تاریخ کے بڑے حصے کو یکسر نظر انداز کرنا ہے۔[8]
اب آئیے دوسرے سوال کی طرف کہ کیا سید احمد ہندو مخالف تھے؟ 1826 میں سید احمد نے برطانوی ہند سے انگریزوں سے لڑنے کے لیے شمال مغربی سرحد کے آزاد قبائلی علاقوں میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ انھوں نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ اس کام کے لیے پوری تیاری کی۔ اتنی بڑی کوشش کے لیے انھیں فنڈ اور رسد کی ضرورت تھی۔ انگریزوں سے لڑنے کے لیے بہت سے ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا۔ چند مثالیں یہ ہیں۔
سید احمد جب ڈلماؤ اور فتح پور سے ہوتے ہوئے گوالیار پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات مہاراجہ دولت راؤ سندھیا سے ہوئی۔ یہ ملاقات غالباً مہاراجہ کے بہنوئی ہندو راؤ کی پہل سے انجام پائی تھی جس کا اس وقت دربار میں کافی اثر و رسوخ تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ سید احمد کے لیے دل میں احترام اور مودت کا جذبہ رکھتا تھا۔ [9] سنہ 1828 میں عثمان زئی کی جنگ کے موقع پر مجاہدین کے دستے نے درانیوں کی کچھ توپیں حاصل کرلیں اور انھیں بعد میں اپنے دشمنوں کے خلاف مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ وقائی میں بیسوارہ کے راجا رام نامی ایک راجپوت کا دل چسپ واقعہ درج ہے جو اس موقع پر مجاہدین کے ساتھ لڑرہا تھا۔ ایک مرحلے پر جب مجاہدین کو تاریکی کی آڑ میں ایک محاذ سے پسپائی کا حکم دیا گیا تو وہ توپوں کے ساتھ اکیلا رہ گیا تاہم رات بھر وہ ان پر گولہ باری کرتا رہا تاکہ دشمن یہ سمجھیں کہ مجاہدین ابھی تک یہاں موجود ہیں۔[10]
یہ ہندو تھے جنھوں نے سید احمد کی نہ صرف فوجی امداد کی بلکہ رسد کا سامان بھی فراہم کیا۔ ہندو بنکروں نے اس مہم کے دوران مسلم مجاہدین کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں قیام الدین احمد کا ایک اقتباس ہم نقل کرتے ہیں۔ ’’ایک اور اہم حقیقت کا ذکر ضروری ہے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، کہ نقد رقم کو سونے کے مہروں میں تبدیل کرنے یا ہنڈیاں تیار کرنے کا کام ہندو بنکروں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ بینکنگ ہاؤسز کے نام سے رام کشن فتو چند (دہلی)، لال چند کرم سنگھ (بنارس)، منوہر داس (پٹنہ)، سمنت رامند شیو بخش، اور منارا (شمالی مغربی سرحد) کے دو بینکروں موتی اور سنتو کے نام درج ہیں۔‘‘ [11]
ان حوالوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جنگ ہندو بمقابلہ مسلمان نہیں تھی۔ اس بات کو اضافی تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ سید احمد کی عام طور پر مسلمانوں کی جانب سے کوئی آؤ بھگت نہیں ہوئی اس کے برخلاف سکھوں کے مقابلے میں مسلم پٹھان سرداروں سے ان کی زیادہ لڑائیاں ہوئیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پشاور میں پیش آیا جہاں سید احمد نے سلطان خان کو شکست دی لیکن فتح کے بعد انھیں مقامی علمائے کرام نے کافر قرار دے دیا۔ اس شدید ردعمل کو دیکھتے ہوئے انھوں نے شکست خوردہ سلطان خان کو بحال کر دیا لیکن جب مقامی پٹھانوں، ہندو سیٹھوں اور ساہوکاروں کو یہ معلوم ہوا تو انھوں نے سید احمد سے درخواست کی کہ وہ سلطان خان کو بحال نہ کریں اور اقتدار اپنے پاس رہنے دیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ہندوؤں کے خلاف مقدس جہاد کررہے تھے تو ہندو راجہ نے ان سے ملاقات اور تعریف کیوں کی؟ مسلمان سرداروں کی طرف سے ان کی مخالفت کیوں کی گئی؟ ہندو سید احمد کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کی فوج میں کیوں شامل ہوئے؟ یہی نہیں بلکہ بعض ہندو بینکاروں نے سید احمد کی افواج کو مالی امداد فراہم کی اور بعد میں انھوں نے اپنی اس امداد میں اضافہ بھی کیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟
وہابیوں پر برطانوی سرکار کے مقدمے اور ہمارا مشترکہ مستقبل
صرف یہی نہیں، بلکہ بعد میں جب انگریزوں نے امبالہ اور پٹنہ میں ان پر عدالتی مقدمات قائم کیے اور ان پر ملکہ برطانیہ کے خلاف جنگ چھیڑنے پر آئی پی سی کی دفعہ 121 کے تحت مقدمہ چلایا تب بھی مسلم مجاہدین کے حق میں بہت سے ہندو گواہ بن کر کھڑے نظر آئے۔ فتحہ، ضلع پٹنہ کے ایک باشندے نندلال کی بھی ایسی ہی کچھ غیرمعمولی مثال ہے، جو غداری کے الزام کا سامنا کررہے مجاہدین کے حق میں گواہی دینے کے لیے دفاعی گواہ کے طور پر امبالہ گیا تھا۔ [12]
مسلمان مجاہدین کو انڈمان کے جزیرہ میں کالے پانی کی سزا اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں بھی ہندو مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور ان کی تدفین میں بھی شریک ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایک مثال یحییٰ علی ہیں، جنھوں نے موت کی سزا پائی اور راس کے جزیرے میں دفن کیے گئے۔ یحییٰ علی کی موت 29 فروری 1868کو ہوئی اور انھیں راس جزیرہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ جنازے میں اس جزیرے کے رہنے والے تقریباً 2500 مسلمانوں کے علاوہ بہت سے ہندوؤں نے بھی شرکت کی۔ [13]
اس سلسلے میں ایک کتاب British Rule and Native Opinion بڑی اہم ہے۔ یہ کتاب بظاہر سید احمد کی تحریک سے غیر متعلق ہے مگر کافی مفید معلومات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف 1870 کی دہائی کے اوائل میں کچھ اہم واقعات کے بارے میں رائے عامہ جاننے کے لیے ہندوستان آیا تھا۔ ان دنوں وہابی تحریک کا کافی چرچا تھا، اس کتاب کا مصنف مالٹہ (1870) اور پٹنہ (1871) میں چل رہے مقدمات کی کارروائی میں موجود تھا اور اس نے اس وقت یہ تبصرہ کیا تھا جو کہ درحقیقت پیشین گوئی تھی، کہ ان عدالتی کاروائیوں کی تاریخ ایک دن ہندوستان میں بڑے فخر کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ [14]
اگر یہ نام نہاد ’’وہابی مجرم‘‘ واقعی ہندو مخالف تھے یا ان سے نفرت اور ان کے خلاف سازش کررہے تھے تو ہندو ان کے جنازے میں کیوں شریک ہوئے؟ انھوں نے ان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کیوں ظاہر کی؟ قابل ذکر حقیقت ہے کہ کالاپانی کے تمام قیدی سیاسی قیدی تھے چاہے ہندو ہوں یا مسلم۔ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے قائدین ہندوستان کے سماجی وسیاسی حالات سے بخوبی واقف تھے۔ اگر مسلمانوں نے ہندوؤں کے خلاف ایسی کوئی سازش رچی ہوتی جس طرح سائی دیپک پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ہندو ناسمجھ تھے کہ اسے سمجھ نہ پاتے؟ یا حقیقت اس سے بالکل مختلف تو نہیں ہے جسے ہندوتوکے حامی پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب آسان ہے۔ تمام ہندوستانی متحدہ طور پر اپنے دشمن انگریز کے خلاف متحد تھے۔ لیکن ہندو قوم پرستی یا ہندوتو کی آڑ میں آج بھی ’’تقسیم کرو اور حکومت کرو‘‘ کے برطانوی ایجنڈہ پر عمل ہورہا ہے جس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔
ولی اللّٰہی تحریک کا خفیہ لٹریچر؟
زبان شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جئے سائی دیپک کا استدلال اس موقف کے ارد گرد گردش کرتا ہے کہ وہابی تحریک کا لٹریچر جان بوجھ کر خفیہ تھا اور اسے فارسی اور عربی میں اس لیے لکھا گیا تھا کہ ایک الگ قومی شناخت کو برقرار رکھا جا سکے اور وسیع تر ہندوستانی معاشرے میں ضم ہونے سے محفوظ رہا جا سکے۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہابی تحریک کا لٹریچر بار بار عرب میں اپنی اصل کی جانب لوٹتا ہے اور ایک خفیہ جہاد کی تبلیغ کرتے ہوئے اور اپنی شناخت کو خالص بنانے کی فکر میں خود کو ہندوستانی (ہندو) عوام سے الگ تھلگ رکھتا ہے۔ لیکن تاریخی شواہد اس دعوے کے برعکس ہیں۔
تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سید احمد نے نہ صرف اردو اور فارسی بلکہ ہندی میں بھی پمفلٹ شائع کروائے تھے۔ سید احمد نے قرآن و حدیث کے مقامی زبان میں ترجمہ کرنے پر بھی زور دیا۔ یہ پمفلٹ زیادہ تر اردو نثر میں لکھے گئے تھے اور ہندی میں بھی چند کاپیاں موجود ہیں۔ اس طرح کی تصانیف، جو کہ اصل میں عربی یا فارسی میں لکھی گئی تھیں، آسان اردو میں ترجمہ کی گئیں، اور ہر صفحہ پر اصل متن اور اردو ترجمہ دونوں ساتھ ساتھ چھاپے گئے۔[15] تاریخی طور پر یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ سید احمد کی جانب سے قرآن و حدیث کے مقامی زبانوں میں ترجمے پر بار بار زور دیا گیا تاکہ لوگ انھیں پڑھ کر سمجھ سکیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ انھوں نے لوگوں کو براہ راست قرآن پڑھنے کی ضرورت اور افادیت پر زور دیا اور ’ہندی زبان‘ میں قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنے کی اہمیت بتلائی۔[16]
شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے مکتب فکر کی اسلامی نشاة ثانیہ، بعد میں سید احمد اور ان کی انقلابی کاوشوں کی تشکیل، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور معاصر ہندوستان کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کو اٹھارہویں صدی کی تحریکوں کی توسیعی شکل کے طور پر پیش کرنا اور ہندوستانی تہذیب کے لیے بیرونی خطرے کے طور پر ان کی تصویر کشی ہندوتوکا سیاسی ہتھکنڈا ہے۔ ماضی کی نشاة ثانیہ کی تحریکیں اپنے اندر جو تاریخی پس منظر رکھتی ہیں وہ عصری جغرافیائی سیاسی مسائل اور سیاسی مقاصد سے پرے ہیں۔ یہ تحریکیں بنیادی طور پر اٹھارہویں صدی کے مغل ہندوستان میں مسلم رسم و رواج اور فقہ کی داخلی اصلاح نو پر مرکوز تھیں۔ ان تحریکوں کو جدید بیانیے سے جوڑنے کی کوشش کرنا دراصل ان کے وسیع تر مذہبی، روحانی اور سماجی پہلوؤں کو نظر انداز کرکے ان کے موقف میں گم راہ کن تحریف کا ارتکاب ہے۔ جئے سائی دیپک نے اپنے تجزیہ کا اختتام سرہندی سے لے کر دہلوی تک، بریلوی سے لے کر علی گڑھ تحریک اور آخر میں دو قومی نظریہ اور ایک عالمی اسلامی فکر کے نظرئیے کو پیش کرکے کیا ہے۔ یہ تاریخ کو غلط طریقے سے پیش کرنے اور اس میں بد دیانتی کے ساتھ تحریف کرنے کا عمل ہے، جو جدید ہندو توا نسل کی ’’تہذیبوں کے تصادم‘‘ کے نظریے کو تقویت پہنچانے کی ایک اور کوشش ہے۔ برطانوی تاریخ دانوں نے ایسے مفسدانہ بیانیوں کی افزائش کے لیے خصوصی کھاد فراہم کی ہے۔
ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کی دہشت پھیلانے کی کوشش
وہابی تحریک پر انگریزی میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے چاہے وہ شائع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ برطانوی حکومت کے وہابیوں کے تئیں نظریہ کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کی حکومت مخالف سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اگرچہ ان کے مذہبی پس منظر کے بارے میں کچھ تفصیل بتلائی جاتی ہے، لیکن وہابیوں کو بنیادی طور پر برطانوی سرکار کے خلاف سازش رچنے والے باغیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی تحریک آزادی کی تاریخ کے بعد کے حصوں میں سید احمد سے ملتی جلتی بہت سی مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں جیسے سبھاش چندر بوس اور بھگت سنگھ۔ تاہم جب مسلمانوں کا معاملہ ہو تو ادب واحترام مفقود ہوجاتا ہے۔
انگریزوں نے انھیں وہابی تحریک جیسا عنوان کیوں دیا؟ وجہ یہ ہے کہ انھوں نے ہندوستانی تحریک آزادی کو ایک نیا نقطہ نظر فراہم کیا اور انگریزوں کے خلاف منظم ہونے کے لیے عوام کو ایک تازہ نقطہ نظر اور خیالات پیش کیے جس کی بدولت 1857 کے غدر نے جنم لیا۔ تاراچند نے اپنی کتاب History of the Freedom Movement in India جلد نمبر 11 میں یہی نقطہ نظر پیش کیا ہے. وہ ولی اللّٰہی تحریک کو ہندوستان کی تحریک آزادی کا حصہ اور ’’مزاحمت وبغاوت‘‘ کے طور شمار کرتے ہیں۔ ولی اللہی تحریک اسی سلسلے کا ایک اہم حصہ ہے، ہم نے ’’ولی اللّٰہی تحریک‘‘ کا عنوان یہیں سے لیا ہے اور انگریزوں کی مروجہ اصطلاح ’’وہابی تحریک‘‘ کے بجائے اسی کو اختیار کیا ہے۔
ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے جن امور کا اپنی کتاب میں خلاصہ کیا ہے، بعض حلقوں کی جانب سے ان پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ انیل سیل[17] (Anil Seal)اور پیٹر ہارڈی (18) (Peter Hardy)جیسے مصنفین کی طرف سے اس تاثر کا اظہار کیا گیا ہے کہ کہ ہنٹر کی کتاب ایک طرح سے ’’سرکاری فرمان کی تکمیل‘‘ اور عملی طور پر ’’نیم سرکاری اشاعت‘‘ تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ برطانوی سرکار کا نمائندہ ہندوستانی مجاہدین آزادی یا انقلابیوں (Revolutionaries) کے خلاف ہی موقف اختیار کرے گا۔ چناں چہ ہندوتو مصنفین کی طرف سے اس برطانوی بیانیہ کا استعمال نہایت افسوس ناک ہے اور ہندوستان کی تکثیری وحدت پر مبنی اقدار کی نفی اور Indic-oriented state power کے قیام کی تائیدہے۔
حوالہ جات
- Maududi, A. A. (n.d.). Tajdeed wa Ahya e Deen (p. 45). New Delhi: MMI Publishers.
- Maududi, A. A. (n.d.). Tajdeed wa Ahya e Deen (p. 89-90). New Delhi: MMI Publishers.
- paper reference ….. I.H.Qureshi – op.cit. P-171. For a detailed discussion on the topic, please see. Mohiuddin Ahmad – Sayyid Ahmad op.cit. P-98 FF and also Masood Alam Nadwi – Hindustan Ke Pehli Islami Tahrik Markazi Maktabat Islami-Delhi 1977. 23…… W.W. Hunter The India Musalmans London 1876. PP.60-61.
- Deepak, J. S. (2021). India, Bharat and Pakistan: The constitutional journey of a sandwiched civilisation (p. 45). New Delhi: Bloomsbury India.
- Mignolo, W. D., & Walsh, C. E. (2018). On Decoloniality: Concepts, Analytics, and Praxis (p. 57). Durham, NC: Duke University Press.
- Mignolo, W. D., & Walsh, C. E. (2018). On Decoloniality: Concepts, Analytics, and Praxis (p. 69). Durham, NC: Duke University Press.
- Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second revised edition, p. 300). New York: Routledge.
- Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second revised edition, p. 194-195). New York: Routledge.
- Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second revised edition, p. 48). New York: Routledge.
- Waqai‘, Tonk ms. f.155 b. Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second re
vised edition, p. 51). New York: Routledge. - Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second revised edition, p. 141). New York: Routledge.
- Mayo Papers, University Library, Cambridge, U.K: Ms. 7490 Box 13, Memorandum by T.E.Ravenshaw.
- Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second revised edition, p. 216). New York: Routledge.
- Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second revised edition, p. 298). New York: Routledge.
- Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second revised edition, p. 281). New York: Routledge.
- Ahmad, Q. (2020). The Wahhabi movement in India (Second revised edition, p. 283). New York: Routledge.
- Seal, A. (1968). The emergence of Indian nationalism: Competition and collaboration in the later nineteenth century. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hardy, P. (1972). The Muslims in British India. Cambridge: Cambridge University Press