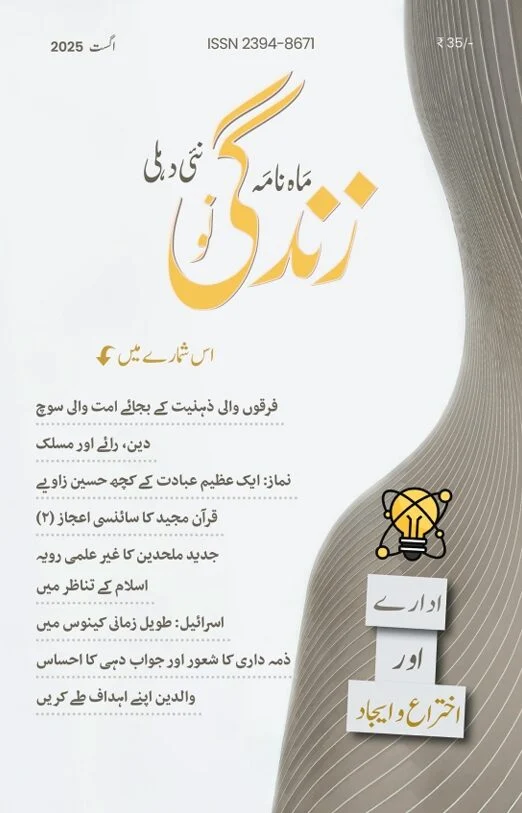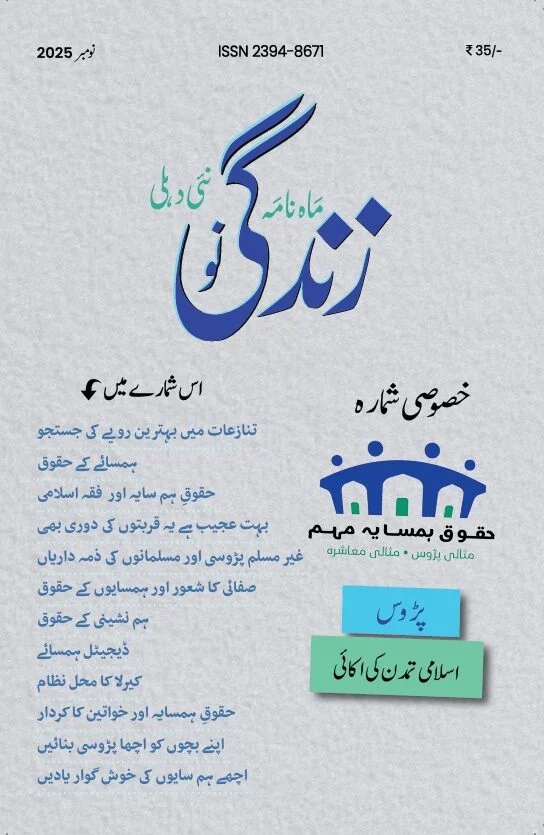اسلام محض ایک مذہبی نظام یا چند عبادات و رسوم کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک ہمہ گیر اور الہامی ضابطۂ حیات ہے، جو وحی کی روشنی میں انسان کو اس کی انفرادی، اجتماعی اور روحانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہ نمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کی بنیاد قرآن مجید پر ہے، جو رب کائنات کا براہ راست کلام ہے، اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کلامِ الٰہی کی عملی اور جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ اسلام کی تعلیمات اپنی اصل میں سادہ، فطری اور آفاقی ہیں، جن کا مقصد انسانی ضمیر کو بیدار کرنا، فکر و عقل کو آزاد کرنا اور انسان کو اس کی فطری راہ پر استوار کرنا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عظیم معجزہ یہی تھا کہ آپ نے دین کو فلسفیانہ موشگافیوں یا مجرد نظریاتی اصطلاحات کے پیچ و خم میں الجھائے بغیر براہ راست انسانی زندگی سے جوڑ دیا۔ وحی کی روشنی میں دین کی تعلیم اس قدر صاف اور فطری تھی کہ عرب کے بدو، بازاروں کے تاجر اور بستیوں کے سادہ لوح انسان بھی اسے سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے۔ نہ اس میں کوئی فکری اصطلاحات کی پیچیدگی تھی، نہ کوئی طبقاتی بندش، نہ کوئی روایتی جمود۔ دین، زندگی کے دھارے میں یوں گھل گیا تھا جیسے پانی میں رنگ، اور انسان اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود، اس اسوہ کو اپنا کر اخلاق، کردار اور علم و حکمت کی نئی منزلوں پر پہنچنے لگا۔
لیکن انسانی تاریخ کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی الہامی یا اصلاحی تحریک اپنی ابتدائی روحانیت اور سادگی کے دور سے آگے بڑھتی ہے تو اس میں ادارہ جاتی جمود، فکری تعصب اور طبقاتی مفادات سرایت کرنے لگتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام مختلف اقوام، تہذیبوں اور تمدنی روایات سے ہم آہنگ ہونے لگا تو امت کے لیے نئے فکری و عملی چیلنج پیدا ہوئے۔ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح، دینی احکام کی وضاحت اور نووارد مسائل میں اجتہادی رہ نمائی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جب فقہ، اصولِ فقہ اور اجتہادی مکاتبِ فکر کا ظہور ہوا۔ اس اجتہادی کوشش میں بلاشبہ وہ اخلاص اور فکری وسعت موجود تھی جو دین کی فطری روح سے ہم آہنگ تھی۔ فقہا نے اپنی بساط کے مطابق امت کی رہ نمائی کی، شریعت کے اصول و ضوابط کو منظم کیا اور دینی علم کو ایک باقاعدہ علمی نظام میں ڈھالا۔
مدینہ، کوفہ، بصرہ، مکہ، مصر اور شام جیسے علمی مراکز میں مختلف فکری و اجتہادی روایات پروان چڑھیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان کے بعد کے فقہا نے امت کے لیے فکری وسعت، علمی گہرائی اور اجتہادی راہیں متعین کیں۔ امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ جیسے مجتہدین نے نہایت احتیاط، دیانت اور اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں فقہی اصول مرتب کیے، جنہوں نے دین کی تعبیر کو منظم اور مربوط کیا۔ ان ائمہ کے مزاج میں وسعتِ فکر، انکساری اور اختلافِ رائے کی گنجائش نمایاں تھی۔ وہ اپنی آرا کو دین کا حرفِ آخر سمجھنے کے قائل نہ تھے۔ امام شافعیؒ کا یہ قول کہ ’’میری رائے درست ہے مگر اس میں غلطی کا احتمال ہے اور مخالف کی رائے غلط ہے مگر اس کے درست ہونے کا امکان ہے‘‘ اس فکری آزادی اور وسعتِ نظر کا مظہر ہے جو اسلام کی اصل روح تھی۔
مگر تاریخ کی کروٹ نے رفتہ رفتہ اس اجتہادی اور فکری وسعت کو محدود کر دیا۔ وہ دین، جو ابتدا میں براہِ راست وحی، سنتِ نبوی اور صحابہ کرام کی عملی زندگی کی روشنی میں اپنی سادگی اور ہمہ گیریت کے ساتھ پروان چڑھ رہا تھا، بتدریج ایک خاص دائرے میں سمٹتا چلا گیا۔ فقہی آرا، جو اصلاً انسانی اجتہاد، فکری کوشش اور نصوصِ شرعیہ کی تفہیم پر مبنی تھیں، انھیں مختلف مسالک اور مکاتبِ فکر کی شکل میں باقاعدہ تقسیم کر دیا گیا۔ ان مسالک نے، جو ابتدا میں علمی تنوع اور اجتہادی اختلاف کی علامت تھے، وقت گزرنے کے ساتھ خود مختار، خود محور اور بعض اوقات ایک دوسرے سے متصادم اداروں کی صورت اختیار کر لی۔
ان مسالک کے قیام میں اگرچہ خلوص، علمی دیانت اور امت کو بدلتے حالات میں منظم دینی رہ نمائی فراہم کرنے کی نیت غالب تھی، لیکن انسانی فطرت، ادارہ جاتی مفادات اور روایتی سوچ کے امتزاج نے اس اجتہادی وسعت کو ایک محدود اور جامد دائرے میں قید کر دیا۔ فقہ، جو ابتدا میں ایک زندہ اور متحرک علمی عمل تھا، اب رفتہ رفتہ ایک بند، تحریری اور حتمی قانون کی شکل اختیار کرنے لگا۔ ایک طرف فقہا اور ائمہ کے اقوال و آرا کو ان کے اپنے زمانے، ماحول اور مخصوص حالات کی رعایت کے بغیر ہر دور اور ہر مقام پر مطلق اور حتمی سمجھا جانے لگا، تو دوسری طرف مسلکی وابستگی کو اس قدر مرکزیت حاصل ہو گئی کہ قرآن و سنت کی براہِ راست تعلیم اور ان کی آزادانہ تفہیم پسِ پشت چلی گئی۔
یہ ایک ایسا علمی اور فکری جمود تھا جس نے دین کی اصل روح، یعنی تحقیق، تدبر اور اجتہاد کو کم زورکر دیا۔ علمی اختلاف کو، جو دراصل وسعتِ فکر اور گہرائی علم کی علامت تھا، مسلکی تعصب اور فرقہ واریت میں بدل دیا گیا۔ ہر مسلک کے پیروکاروں نے اپنے اپنے فقہی ڈھانچوں کو دین کی مکمل اور حتمی شکل قرار دینا شروع کر دیا۔ اس صورتحال میں وہ علمی رویہ، جس میں امام مالکؒ جیسی شخصیات یہ کہتی تھیں کہ ’’ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے اور رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اس صاحبِ قبر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے‘‘، رفتہ رفتہ کم زورہوتا چلا گیا۔ مسالک اپنی حدود سے نکل کر ایسی مذہبی شناخت بن گئے، جنھیں چیلنج کرنا گویا دین کو چیلنج کرنے کے مترادف سمجھا جانے لگا۔
یوں دینی علم، جو ابتدا میں اللہ کی رضا، امت کی فکری رہ نمائی اور معاشرتی اصلاح کا ذریعہ تھا، اب مخصوص فقہی سانچوں، مسلکی حدود اور ادارہ جاتی بقا کا محور بن گیا۔ مسالک کے اندر تنقید، تجدید اور اجتہاد کی گنجائش کم ہوتی گئی اور ہر مکتبِ فکر اپنے اپنے دائرے میں علمی خود کفالت اور بعض اوقات علمی بالادستی کے احساس میں مبتلا ہو گیا۔ نتیجتاً، دین کے وہ اجزائے اصلیہ، جو براہِ راست وحی، سنت اور اجتہادی بصیرت سے جُڑے تھے، ان پر پردے پڑتے گئے اور امت علمی جمود و رکود، فکری تعصب اور مسلکی تقسیم کی گرفت میں آتی چلی گئی۔
یہی وہ تاریخی موڑ تھا، جس نے دین کو اس کی ہمہ گیریت، سادگی اور اجتہادی وسعت سے جدا کر کے محدود سانچوں اور جامد و متصلب بلکہ متعصب اداروں کے تابع کر دیا، اور امت کے فکری زوال اور دینی بگاڑ کی بنیادیں رکھ دیں۔ چوتھی صدی ہجری کے بعد اسلامی دنیا میں دو ایسے رجحانات پیدا ہوئے، جنہوں نے دین کی اصل روح کو متاثر کیا اور امت کو فکری جمود، مسلکی تعصب اور علمی انحطاط کے دائرے میں جکڑ دیا۔
ایک طرف دینی علم، جو ابتدا میں خالص اللہ کی رضا اور انسانیت کی اصلاح کا ذریعہ تھا، آہستہ آہستہ مسلكى وراثت، معاشی مفاد اور ادارہ جاتی بقا کا ذریعہ بن گیا۔ مدارس اور مذہبی ادارے، جو کبھی قرآن و سنت کی تعلیم، اجتہادی بصیرت اور دینی خدمت کے مراکز ہوا کرتے تھے، مسلکی، خاندانی اور علاقائی تعصبات کے اسیر بن گئے۔ دین کی تعلیم محدود ہو کر مخصوص فقہی مسالک، درسی کتب اور ادارہ جاتی وابستگی تک محدود ہو گئی، اور طالب علموں کو براہِ راست قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کی اجازت دینے کی روایت کم زورپڑتی چلی گئی۔ دینی خدمت کی جگہ مسلکی دفاع، علمی تحقیق کی جگہ رسمی تعلیم، اور خلوص کی جگہ معاشی مجبوری نے لے لی۔ اس رویے نے نہ صرف علمی جمود کو فروغ دیا بلکہ دین کو طبقاتی و مسلکی مفادات کا اسیر بنا دیا، جس کی جڑیں آج بھی امت کے فکری زوال میں دیکھی جا سکتی ہیں۔
دوسری جانب، کچھ علما نے دین کی سادگی، فطری استقامت اور نبوی ماڈل کو چھوڑ کر اس میں یونانی فلسفے، منطق اور قدیم عقلی نظاموں کی آمیزش شروع کر دی۔ افلاطون اور ارسطو جیسے فلسفیوں کے نظریات کو دین کی علمی گہرائی کا معیار سمجھا جانے لگا اور اس بات کو فراموش کر دیا گیا کہ قرآن و سنت کی اصل طاقت اس کی فطری وضاحت، سادہ اسلوب اور انسان کے قلب و عقل دونوں کو متاثر کرنے والی جامعیت میں ہے۔ فلسفے اور منطق کی یہ آمیزش دین کو عام انسان کی سمجھ سے دور لے گئی۔ یوں دین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاص، عاجزی، خدمت اور سچائی کا مظہر تھا، رفتہ رفتہ فلسفیانہ موشگافیوں اور مناظرانہ اصطلاحات میں الجھ کر رہ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی سچائی اور اثر انگیزی عام مسلمان کی زندگی سے دور ہوتی گئی اور ایک محدود، خواص زدہ اور پیچیدہ دائرہ بن کر رہ گئی۔
برصغیر پاک و ہند کی دینی روایت میں یہ دونوں رجحانات شدت سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مدارس میں تعلیم کا محور زیادہ تر مخصوص فقہی مسلک، عقائد کی محدود تفہیم اور صوفی سلسلوں کی ترویج رہا۔ قرآن و سنت کو محض تائیدی حیثیت دی گئی اور بسا اوقات ایسی روایات کو بھی مسلک کی تائید میں فوقیت دی گئی، جو نہ صرف ضعیف بلکہ بعض اوقات قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے منافی تھیں۔ مسلکی وابستگی اس قدر شدید ہو گئی کہ فقہ و عقائد کے علاوہ مدارس میں علمی سوال اٹھانے، اجتہادی سوچ اپنانے یا براہِ راست قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا دروازہ عملاً بند کر دیا گیا۔ اکابر پرستی کی ایسی فضا پیدا کی گئی کہ ان کے اقوال اور فتاویٰ کو حرفِ آخر سمجھنا دینی تقاضا قرار پایا، خواہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کتنے ہی کم زورکیوں نہ ہوں۔
اس کے باوجود کچھ ایسے ادارے اور فکر کی ایسی روایات باقی رہیں جنہوں نے دین کو مسلکی تعصب، ادارہ جاتی جمود اور فلسفیانہ پیچیدگیوں سے آزاد رکھنے کی جدوجہد کی۔ ان کی تعلیم و تربیت کا محور صرف قرآن و سنت کی براہِ راست تعلیم، اجتہادی بصیرت کی ترویج اور دینی سچائی کی غیر مشروط تلاش رہی۔ یہی وہ راستہ ہے جو اسلام کی اصل روح سے ہم آہنگ ہے اور جو امت کو دوبارہ فکری آزادی، دینی خلوص اور علمی تازگی کی طرف لے جا سکتا ہے۔
آج امتِ مسلمہ ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں دین کی اصل سچائی کو مسلکی تعصب، اکابر پرستی، فلسفیانہ الجھاؤ اور ادارہ جاتی جمود کے پردوں سے نکال کر سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ فقہ، اجتہاد اور علمی مکاتبِ فکر کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر جب انھیں قرآن و سنت کی بالادستی پر مسلط کر دیا جائے، فکری آزادی کو محدود کر دیا جائے، اور دین کو مخصوص طبقات اور اداروں کے تحفظ تک محدود کر دیا جائے تو نتیجہ صرف علمی زوال، فکری انتشار اور دینی بے روحی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
دینِ اسلام کی بقا، اس کی سچائی کی بحالی اور امت کی فکری ترقی اس میں ہے کہ ہم دین کی تعبیر کو دوبارہ وحی کی روشنی، سنتِ نبوی کی سادگی، اجتہاد کی وسعت اور امت کے اجتماعی شعور کی بنیاد پر استوار کریں۔ جب تک دین کو فلسفے کی الجھنوں، فقہی جمود اور ادارہ جاتی مفادات سے آزاد نہیں کیا جاتا، نہ دین کی اصل روح باقی رہ سکتی ہے، نہ امت کی فکری تازگی، اور نہ ہی وہ وحدت و یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے جو امت کو زمانے کی قیادت کا اہل بنا سکے۔