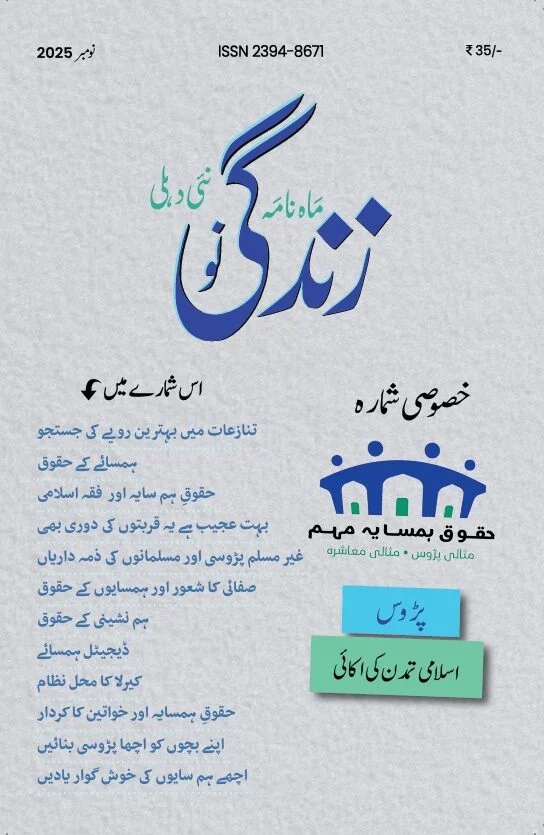اس سلسلہ مضامین کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ فلاحی ادارے کس طرح اسلام کی شہادت کا موثر ذریعہ بن سکتے ہیں؟ کچھ اصولی باتوں پر گفتگو کے بعد اسلامی تاریخ کے ادارہ جاتی کاموں کے ماڈل کے طور پر ہم وقف کے ادارے کو زیر بحث لاچکے ہیں۔ علاوہ ازیں، شفاخانوں، رفاہ عام کے اداروں اور علمی و تحقیقی اداروں پر الگ الگ قسطوں میں تفصیل سے گفتگو ہوچکی ہے۔ اس سلسلے کے اگلے حصے میں مالیاتی اداروں اور تعلیمی اداروں پر گفتگو پیش نظر ہے اور ان کے علاوہ ‘دیگر اداروں’ کے عنوان سے مختلف النوع شعبوں سے تعلق رکھنے والے اداروں کو بھی زیر بحث لانے کا ارادہ ہے۔ ان شاء اللہ۔
لیکن اس دفعہ الگ الگ شعبوں سے متعلق اداروں کی بحث کے سلسلے کو ملتوی کرکے اداروں کے نظم و انتظام سے متعلق کچھ گذارشات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ان گذارشات کا تعلق تمام طرح کے اداروں سے ہے۔
ادارہ سازی اور اداروں کے حسن انتظام کی صلاحیت قوموں کے لیے بھی اور تحریکوں کے لیے بھی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ صلاحیت کئی ذیلی صلاحیتوں سے عبارت ہے۔ ذیل کی سطروں میں اس سے متعلق کچھ ایسے پہلو پیش کیے جارہے ہیں جن پرہمارے خیال میں، ہمارے اداروں میں توجہ کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے جو ادارے ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کی ناکامی کا سبب ان پہلوؤں کے سلسلے میں غفلت ہی ہے۔ تحریک اسلامی اور اس کے وابستگان کے ذریعے قائم کردہ بعض اداروں میں بھی ہمارے خیال میں یہی کم زوریاں اصل مسئلہ بن رہی ہیں۔ تحریک اور اس کے وابستگان کے جو ادارے کام یابی کی طرف گام زن ہیں، وہاں یہ کمزوریاں نظر نہیں آتیں۔ ان کم زوریوں پر قابو پائے بغیر ادارے وہ مقاصد حاصل نہیں کرسکتے جن پراس سلسلہ مضامین میں بحث کی جارہی ہے۔
اس وقت اگر ہمارے بعض حلقوں میں یہ خیال ہے کہ ادارے بجائے اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بننے کے، تحریکوں کے لیے بوجھ اور ان کے پیروں کی زنجیریں بن رہے ہیں تو اس کی اصل وجہ یہی کم زوریاں ہیں۔ اسلامی تاریخ کے جن روشن ادوار کی مثالیں ہم پیش کررہے ہیں ان میں اداروں کی کام یابی کا اصل سبب ان کم زوریوں سے پاک ہونا تھا اور آج بھی جو ادارے کامیاب ہیں، خواہ ہمارے ادارے ہوں یا دیگر تحریکوں کے، وہ اسی لیے کام یاب ہیں کہ اداروں کی کام یابی کے ان بنیادی عوامل کے سلسلے میں وہ حساس ہیں اور ان عوامل کو کنٹرول میں رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت برسوں کی ریاضت سے انہوں نے پیدا کی ہے ۔[1] اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے نظم و انصرام اور قیادت و رہنمائی سے متعلق ان پہلوؤں پر خاص توجہ اور ان کے حوالے سے مزاج اور طرز کار میں اساسی تبدیلیاں ہماری اہم ترجیح ہونی چاہیے۔
ادارہ جاتی سوچ (Institutional Thinking)
اداروں کی کام یابی کی پہلی ضرورت ادارہ جاتی سوچ ہے۔ ادارہ جاتی سوچ سے ہماری مراد محض فلاحی و رفاہی اداروں کو چلانے کی صلاحیت نہیں بلکہ ہر طرح کی انسانی اجتماعیت اور اس کے مفاد کو پیش نظر رکھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک فرد کے تنہا کام کرنے کے انداز و طریقے میں اور ایک مستحکم، پائیدار اور خود کفیل ادارے کے قیام و ارتقا کی حرکیات (dynamics)میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے اکثر ادارے اسی اساسی سطح پر ناکام ہوجاتے ہیں۔
ادارہ جاتی سوچ ایک خاص مائنڈسیٹ اور طرز کارکا نام ہے۔ اجتماعیت کے مقاصد، اس کی اقدار(values)، اس کی اساس پر پائیدار تنظیمی کلچر اور ایک ایسے مستقل نظام کو پروان چڑھانے کی فکر مندی جس کے ذریعےاجتماعیت خود اپنے مقاصد اور اقدار کے لیے کام کرتی رہے، اس کو ادارہ جاتی سوچ کہتے ہیں ۔ [2]
اس سوچ کے حامل لوگ جب ادارہ بناتے ہیں تو دسیوں سال آگے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ادارے کے حال سے زیادہ مستقبل پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ وہ ادارے کو اپنے آپ پر منحصر نہیں رکھتے بلکہ ایسے خود کار نظام (systems) اور طریق کار (processes)قائم کردینے پر ان کی اصل توجہ ہوتی ہے کہ قائم کرنے والوں کے بعد بھی اور ان کے بغیر بھی ادارہ کام یابی سے چلتا رہے۔ وہ ادارے کو ہر اعتبار سے خود کفیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادارے کی خود کفیلی(self-sustainability) اور خود کاری (automatisation)ان کی توجہات کا اصل مرکز ہوتی ہے ۔[3]
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ادارہ مالی لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ اس کو اس کی ضرورت کے مطابق مالیات فراہم ہوتی رہے یا وہ آزادانہ اپنے وسائل خود حاصل کرتا رہے۔ اس میں ایسی پالیسیاں، معیارات(standards)، پروسیس اور سب سے بڑھ کر ایسا تنظیمی کلچر فروغ پائے کہ وہ اپنے دستور اور اپنی پالیسی کے مطابق آزادانہ چلتا رہے اور کسی کی طرف بھی بلکہ بانیوں اور مالکوں کی طرف بھی رجوع کرنے کی اسے ضرورت نہ پڑے۔ فرائض و اختیارات کی واضح تقسیم ہو اور اس کے مطابق سب آزادانہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں۔ جو لوگ بھی ادارے کے دستور کے مطابق ذمے دار بنائے جائیں وہ پوری طرح بااختیار ہوں اور مکمل اختیار کے ساتھ مکمل ذمے داری ادا کریں ۔[4]
دنیا بھر کے اداروں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو ادارے نسل در نسل کام یابی سے چلتے رہے، ان کےبانی یہی ادارہ جاتی سوچ رکھتے تھے۔
ادارہ جاتی سوچ اسلامی تراث کا ایک اہم جزو رہی ہے۔ مشہور اسلامی مفکر ڈاکٹر محمد عمارہ نے اپنے ایک مقالے[5] میں تفصیل سے واضح کیا ہے کہ ادارہ جاتی سوچ (المؤسسیة)اسلام کا امتیاز ہے[6]۔ اسلام دین الجماعۃ (اجتماعیت پسند دین) ہے اور اول روز سے قبیلہ، امت، حکومت (الدولۃ) جیسے اساسی تصورات کے ذریعے اور پھر ان کے ذیل میں زکوة، وقف، حسبہ، قضا، شوریٰ کے ذریعے ادارہ جاتی سوچ کو اس نے پروان چڑھایا ہے[7]۔ شارع نے عبادات تک کے ذریعے سے ادارہ جاتی سوچ کو پروان چڑھایا ہے۔ باجماعت نماز میں ڈیڑھ ہزار سال سے مسلمان مخصوص معیارات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ امام اور مقتدیوں کے فرائض، اختیارات اور حدود متعین ہیں جن کی رتی برابر خلاف ورزی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ نماز کے تمام مراحل اور پروسیس کا مکمل فلوچارٹ بہترین طریقے سے متعین well-defined ہے اور اس پروسیس سے معمولی گریز بھی طاقت ور سے طاقت ور آدمی کے لیے ناممکن ہے۔ اسی کو آج ادارہ جاتی سوچ کہا جاتا ہے۔ نماز کے علاوہ زکوة، حج، روزہ میں بھی ادارہ جاتی سوچ (المؤسسیة)کے وہ سارے عناصر نہایت موثر طریقے سے شامل کردیے گئے ہیں جو ہمیں جدید لٹریچر میں ملتے ہیں۔ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اسلامی تاریخ میں بالکل شروع ہی سے ادارہ جاتی طرز کار یعنی اجتماعیت پسند مزاج مسلمانوں میں تیزی سے فروغ پانے لگا۔
علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں حضرت عمرؓ کی ‘اولیات’ (یعنی وہ نئی چیزیں جو حضرت عمرؓ نے شروع کیں) کی جو تفصیل بیان کی ہے ان میں سے اکثر کا تعلق ادارہ جاتی نظام institutionalization سے ہے[8] یعنی جو امور سابقہ ادوار میں ذمے داروں کے انفرادی یا شورائی وقتی فیصلوں سے انجام پاتے تھے، حضرت عمرؓ نے انہیں باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دی اور طرح طرح کے ایسے پائیدار اور مستقل ادارے قائم کردیے جو خود سے کام کرتے رہیں اور ذمے داروں کی بار بار توجہ اور فیصلوں کے محتاج نہ رہیں۔ (تفصیل کے لیے ‘الفاروق’ کا محولہ باب ملاحظہ فرمائیں)۔ بعد کے ادوار میں ہر زمانے میں مسلمانوں نے اس ادارہ جاتی رجحان کو آگے بڑھایا جس کی تاریخی تفصیل اس سلسلہ مضامین میں بھی متعدد بار زیر بحث آچکی ہے اور خاص طور پر وقف کا ادارہ اس ادارہ جاتی سوچ کا بڑا خوبصورت نمونہ ہے۔ [9]
حالیہ ادوار میں جماعت اسلامی کا تنظیمی نظام بھی مولانا مودودیؒ اور ان کے رفقا کی مستحکم ادارہ جاتی سوچ کا غماز ہے ۔[10] (اوپردرج بات پیش نظر رہے کہ ادارہ جاتی سوچ کا تعلق صرف فلاحی اداروں سے نہیں بلکہ ہر طرح کی اجتماعیتوں سے ہے) اپنے دور کے مذہبی حلقوں کے عام رواج کے برخلاف، مولانا مودودیؒ نے جماعت کو نہ اپنی ذات پر منحصر رکھا اور نہ اپنے خاندان یا اولاد پر اورنہ ہی اپنے بعد اپنے متعین کردہ کسی جانشین کو جماعت کی بقا و تسلسل کے لیے ناگزیر سمجھا۔ مقصد و نصب العین، طریق کار، دستور، ضابطے اور واضح اقدار کی اساسیات پرخود کار نظام جماعت کا ایسا پائیدار کلچرقائم کردیا جو آٹھ دہوں کے بعد آج بھی برصغیر کے مختلف علاقوں میں بہتر طریقے سے آزادانہ کام کررہا ہے۔
اس بات کی ضرورت ہے کہ یہی ادارہ جاتی سوچ اور ادارہ جاتی طرز کار ہمارے اداروں میں بھی فروغ پائے۔ ادارہ جاتی سوچ کیا ہے اور وہ کیسے روایتی سوچ سے مختلف ہے؟ درج ذیل جدول سے اس کی وضاحت ہوگی۔

اس جدول کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ‘غیر ادارہ جاتی مزاج’(non-institutional thinking) ہمارے یعنی مسلمانوں کے اکثر اداروں کی ناکامی کا ایک بڑا سبب ہے۔
قیادت و انتظام
دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے خیال میں قیادت (leadership) اور انتظام (management)میں کنفیوژن کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اکثر اداروں کو اس مسئلے نے بھی مفلوج کررکھا ہے۔
قیادت اور انتظام میں فرق کی بحث جدید علم انتظام کی ایک اہم بحث ہے ۔[11] تنظیمی معیارات کی بحث میں، اداروں کی ناپختگی immaturity کی ایک اہم علامت یہ مانی جاتی ہے کہ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے دائروں کے سلسلے میں کنفیوژن پایا جائے یا ان میں خلط مبحث ہو ۔[12] اس طرح کے خلط مبحث کو ماہرین اکثر اداروں کی ناکامی کا بڑا سبب سمجھتے ہیں [13]۔ اس لیے بعض ماہرین ان دونوں کرداروں کو بالکل الگ الگ رکھنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ [14]
اہل اسلام کے لیے یہ طرز فکر بھی نیا نہیں ہے۔ کلاسیکی اسلامی فکر میں بھی اس حوالے سے ٹھوس اشارے ملتے ہیں۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک اہم بحث خلافت (الخطط الدّینیة المختصّة بالخلافة) اور سلطانی (الخطط الملوكیة السّلطانیة) کے حوالے سے کی ہے اور اسلامی خلافت کی مثالی شکل یہ بتائی ہے کہ خلیفہ کا ارتکاز مملکت کی دینی شناخت، دینی فرائض اور اسلامی مقاصد پر ہو (جس کی فہرست بھی ابن خلدون نے بیان کی ہے) اور خلیفہ کی نگرانی میں مملکت کے شعبے اور اعوان(نظام سلطانی) انتظامی امور پر توجہ دیں۔[15] اسلامی حکمرانوں نے اسی طرز فکر کے تحت دیوان اور مجالس وزراء و وزیر اعظم کے عہدوں کو رائج کیا۔ مدارس عربیہ میں مہتمم اور ناظم کے الگ الگ مناصب تشکیل پائے اور صدر وسکریٹری کی مروج تقسیم کار اسلامی تنظیموں میں بھی فروغ پائی۔
قیادت کا اصل کام ادارے کا وژن متعین کرنا، اس کی قدروں کو واضح کرنا، اس کا منفرد کردارطےکرنا یعنی اس کی مجموعی سمت کا تعین کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ادارہ اپنے وژن، مقصد، اور اقدار کے مطابق کام کرتا رہے ۔[16] اس سلسلہ مضامین میں ہم مختلف میدانوں سے متعلق اسلامی اداروں کا امتیازی کردار واضح کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ ان کی اساسی قدریں core valuesکیا ہوں؟ سمت کار کیا ہو؟ وہ کیسے دیگر اداروں سے مختلف و منفرد ہوں؟ اور کیسے اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بنیں؟ ان سب امور کا تفصیلی تعین اور ادارے کی اس سے ہم آہنگی کو یقینی بنانا، یہی قیادت کا اصل کام ہے۔
اس کے مقابلے میں انتظامیہ کا کام ادارے کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر رکھنا ہے۔ ادارہ جو بھی کام کررہا ہے اور جو خدمات فراہم کررہا ہے وہ معیاری ہوں، کم سے کم خرچ میں اچھے سے اچھا کام ہو، ادارہ مالی لحاظ سے خود کفیل ہو، اسٹاف باصلاحیت ہو، اس کی پرفارمنس اچھی سے اچھی ہو، جو منصوبے اور اہداف طے کیے جائیں وہ پورے ہوں۔ ان سب کو یقینی بنانا انتظامیہ یا مینجمنٹ کا کام ہے ۔[17]
یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے what؟،اس کا تعلق قیادت سے ہے اور کیسے کیا جائےhow؟،اس کا تعلق انتظامیہ سے ہے۔ جو کام بھی کیا جائے وہ درست اور صحیح ہو، doing right things اس کا تعلق قیادت سے اور جو کام بھی کیا جائے وہ اچھے اور معیاری طریقے سے ہو doing things right اس کا تعلق انتظامیہ سے ہے ۔[18]
قیادت اور انتظامیہ کے آلات و وسائل کار میں بھی فرق ہے۔ قیادت اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تربیت و ذہن سازی، ترغیب و تحریک، لوگوں کو انسپائر کرنے کی کوشش، ادارے کے کلچر پر اثر انداز ہونے کی کوشش، کمیونکیشن، دلائل اور فکر کی قوت، نیز ذاتی کشش اور اخلاقی اثر سے کام لیتی ہے۔ جب کہ انتظامیہ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضابطہ، قانون، اختیارات، انعام و سزا، کنٹرول، فیصلے اور ان کی منظوریاں، مالیاتی کنٹرول وغیرہ جیسے تنظیمی طریقوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے ۔[19] اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر صورت میں وسائل کی اس تقسیم کو حرف آخر سمجھ لیا جائے۔ انتظامیہ بھی ضابطہ اور قانون کے علاوہ اخلاقی اور فکری اثر سے کام لے گی اور ناگزیر صورتوں میں ضروری قدم اٹھانے کا اختیار بھی قیادت کو حاصل ہوگا اور اسے اس طرح کا اختیار دیا جانا چاہیے، لیکن عام طور پر، اور زیادہ تر، قیادت اور انتظامیہ کے کام کے وسائل کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سلسلے میں تصور واضح رہنا چاہیے۔
تحریکی اداروں میں تحریک کا اصل کردار قیادت کا کردار ہے۔ اوپر جتنے کام قیادت کے بتائے گئے ہیں وہ تحریکی قیادتوں کو اپنے اور پرائے، ہر طرح کے اداروں میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ واضح کیا گیا، ان کاموں کو کرنے کے لیے ضابطے اور اختیار کی، کنٹرول اور اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے، محض اخلاقی اور فکری اثر اور مسلسل ربط، گفتگو اور شخصی اثر کافی ہے۔ (ناگزیر حالات کا معاملہ الگ ہے) یہ کردار ہر طرح کے اداروں میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے تحریکوں کا انداز کار ‘قلعے فتح کرنے کا’ یعنی زیادہ سے زیادہ اداروں پر اثرانداز ہوکر وہاں صحیح فکر، صحیح روایات اور صحیح کلچر کو فروغ دینے کا ہوتا ہے۔ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے نہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے نہ پیسے کی۔ نہ مالکانہ قبضے اور اختیارات و کنٹرول کی کشمکش درکار ہے نہ عہدوں و مناصب کی دوڑ میں فریق بننے کی۔ خیر خواہی کا سچا جذبہ اور فکری و اخلاقی اثر انگیزی کی تحریکی اسپرٹ ملک وملت کے متعدد اداروں کو درست رخ دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے قیادتی کردار، زیادہ سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ اداروں میں ادا کیا جاسکتا ہے اور اسی کردار سے تحریکیں معاشرے کی تعمیر کا فریضہ انجام دینے کے لائق بنتی ہیں۔
اس کے مقابلے میں اوپر جو کام انتظامیہ یا مینجمنٹ کے بتائے گئے ہیں وہ اصلاً ماہرین کے کام ہیں اور انہی کو تفویض کیے جانے چاہئیں۔ اسکول کا تجربہ کار پرنسپل، ماہر ڈاکٹر یا ہاسپٹل مینیجر، مالیاتی امور کا ماہر، محقق و اسکالر، ماہر تجارتی منتظم (business administrator) وغیرہ لوگ جو اپنے اپنے میدانوں کے مسلمہ ماہرہوں، وہ اداروں کے ذمے دار بنائے جائیں۔ سوسائٹی یا ٹرسٹ میں بھی متعلق صلاحیت رکھنے والے لوگ ہوں اور خاص طور پر وہ لوگ جن پر ادارے کی انتظامی ذمے داری ہو (سکریٹری، مینیجنگ ٹرسٹی وغیرہ) وہ ضرور ایسے لوگ ہوں جو ضروری نظریاتی و اخلاقی امتیاز کے بھی حامل ہوں لیکن اصلاً متعلقہ میدان میں مہارت ان کی قابلیت ہو۔ ایسے ماہر منتظمین، جب زیادہ سے زیادہ اختیارات کے ساتھ اور زیادہ سے زیادہ آزادی کے ساتھ کام کریں گے اور روزمرہ کے امور (micromanagement) میں کسی مداخلت کا انہیں سامنا نہیں ہوگا تو ادارے کی کارکردگی بہترہوگی۔
اداروں کی ناکامی کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ منتظمین کو کام کی آزادی نہیں ہوتی۔ ملت کے اداروں میں بڑے پیر صاحب یا مولانا صاحب اور ان کے اہل خاندان اور تحریکی اداروں میں امیر صاحب یا ان کے اہل شوریٰ، ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں مخل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ بجائے قیادت کا کردار ادا کرنے کے انتظامیہ کا کردار ادا کرنے لگتے ہیں۔ روز مرہ کے امور کا انصرام خود کرنے لگتے ہیں۔ اسٹاف کی تقرری اور برخاستگی، مالی امور، روزمرہ کے انتظامی مسائل اور تنازعات کے حل وغیرہ امور یعنی روز مرہ کے انصرام کی ذمہ داریوں میں بتدریج شمولیت بڑھانے لگتے ہیں۔ یہ ایک اٹل اصول ہے کہ جب قیادت کسی کام کا چارج لے لیتی ہے تو انتظامیہ خود بخود اس سے دستبردار ہوجاتی ہے۔
اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان قیادتی عمل کا ہوتا ہے۔ ادارے کے وژن، سمت اور اس کی اقدار کی پاسبانی کا جو کام قیادت سے وابستہ ہے اور جو قیادت کا اصل میدان ہے، اس کام پر توجہ نہیں ہوپاتی۔ ان کاموں کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ انتظامی الجھنوں میں شامل ہونے والے افراد بالعموم انہیں انجام دینے کی پوزیشن سے محروم ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے قیادت کا عمل عملاً ختم ہوجاتا ہے یعنی سمت کار، مقصد، اور اساسی اقدار سے وابستگی مجروح ہونے لگتی ہے۔ ادارے کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ ادارہ دسیوں اداروں میں ایک ادارہ بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ نہ اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بن پاتا ہے اور نہ اس کا اسلامی و تحریکی امتیاز نمایاں ہوپاتا ہے۔ محض ادارے کا چلتے رہنا (بلکہ گھسٹتے رہنا) کام یابی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور لوگ اسی پر مطمئن رہتے ہیں۔
دوسری طرف انتظامی عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ انتظام کے کام کی صلاحیت اوراختصاص چونکہ قیادت کے اندر نہیں ہوتا (امیر ہونے، مولانا ہونے یا رکن شوریٰ ہونے سے کوئی ہاسپٹل مینیجمنٹ کے فن کا ماہر نہیں بن جاتا) اس لیے وہ کام بھی متاثر ہوجاتا ہے۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اکثر ادارے ہمارے ملک میں اسی مسئلے کے شکار ہیں۔ اسلامی رہنماؤں کا کام اداروں کو اسلامی شناخت فراہم کرنا، انہیں اسلامی طرز حیات کی مخصوص خاصیتوں کا آئینہ دار بنانا اور اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بنانا ہے۔ یہی ان کے مقام و منصب کا تقاضا ہے اور یہی ان کا تخصص ہے۔ اسے چھوڑ کر اور نظر انداز کرکے وہ اداروں کے روزمرہ کے انتظامات(micromanagement)میں لگ جاتے ہیں تو جن ماہرین کو اس طرح کا انتظام اصلاً کرنا ہے وہ اختیارات سے محروم ہوجاتے ہیں اوران کی صلاحیتیں اور تجربات بے فیض رہ جاتے ہیں۔
ذیل کے جدول میں ہم اداروں کے دونوں طرح کے کاموں کا خلاصہ درج کررہے ہیں، وہ کام بھی جو تحریکوں کے کرنے کے ہیں اور وہ کام بھی جو ماہرین کے ذریعے -زیادہ سے زیادہ آزادی کے ساتھ- انجام دیے جانے ہیں۔

کچھ اور اصول
اوپر کی سطروں میں بیان کردہ دو اہم اصولوں کے ساتھ اداروں کےنظم و انتظام کے کچھ اور اہم اصول بھی ہیں۔ تحریک اور امت میں موجود اداروں کے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر درج ذیل کچھ اصولوں کا تذکرہ ہم ضروری سمجھتے ہیں۔
پہلا اصول: اختیار اور ذمے داری ہمیشہ ایک دوسرے کے تناسب میں ہوتے ہیں۔[25] (Powersand Responsibility are always proportional to each other)
یہ اصول اسلامی فکری روایات میں شروع سے معروف رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت لا یکلف اللہ نفسًا الا وسعھا (اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا) سے بھی اس اصول کے حق میں استدلال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاغذ میں کچھ بھی لکھ لیں، فطرت کا اصول یہی ہے کہ اداروں میں عملاً، ذمے داری اور احساس ذمہ داری کا تعین اختیارات سے ہوتا ہے۔ انتظامی سطح پر (قیادت کی سطح پر نہیں، وہاں اصول دوسرا ہے) بڑا اختیار ہی بڑی ذمے داری پیدا کرتا ہے اور بڑی ذمے داری کے لیے بڑا اختیار ناگزیر ہوتا ہے۔ اداروں کی ناکامی کا ایک بڑ ا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اداروں کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں انہیں ضروری اختیارات نہیں دیے جاتے، جس کے نتیجے میں ان کی کارکردگی متاثر ہوجاتی ہے۔ ذمہ دار کوئی اور ہوتا ہے اور اختیارات کسی اور کے پاس ہوتے ہیں۔
ادارے کے مالک نے، اس کے خاندان نے، امیر نے، شوریٰ نے اختیارات اپنے پاس رکھے، خود فیصلے کرنے شروع کیے یا انتظامیہ کے ہر فیصلے کو اپنی توثیق و منظوری کا پابند بنادیا تو اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ادارے کا ٹرسٹ یا سوسائٹی یا اس کا منتظم عملاً ذمے دار باقی نہیں رہا۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہی نہیں ہوسکتا کہ اسے ذمے داری سے فیصلے کرنے ہیں، انہیں نافذ کرنا ہے اور ان کے اچھے اور برے نتائج کی ذمے داری قبول کرنی ہے۔ جب کسی سے اختیار لے لیا جاتا ہے تو عملاً اس سے ذمے داری بھی لے لی جاتی ہے۔ اب ذمے داری کا سارا بوجھ آپ کے سر آگیا۔
اداروں میں باصلاحیت لوگ مقرر کیے جائیں، اچھا تعلیم یافتہ تجربہ کار پرنسپل، ماہر ڈاکٹر، بہترین تجارتی منتظم دستیاب ہو لیکن اختیارات اسے کچھ نہ ہوں، ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے لیے اسے قیادت سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو تو اس باصلاحیت فرد کو آپ جس نام کے عہدے سے بھی یاد کریں، وہ عملاً ذمہ دار نہیں ہے۔ بلکہ قیادت نے ذمے داری اپنے پاس ہی رکھی ہے۔
قیادت کے اصل کام تین ہیں۔ انتظام کے لیے بہتر سے بہتر لوگوں کو منتخب کرنا، ان کو اپنی اقدار اور فلسفے کی مؤثر ترین تعلیم دینا اور پھر ان پر اعتماد کرکے انتظامی امور کو زیادہ سے زیادہ ان کے حوالے کردینا۔ ناگزیر صورتوں میں قیادتوں کو مداخلت بھی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا بہانہ بناکر روز مرہ کے امور میں جب قیادتیں مداخلت کرنے لگتی ہیں تو وہ پورے نظام کو کم زور کردینے کا ذریعہ بنتی ہیں۔
دوسرا اصول: ادارے کی اصل طاقت اس سرمایہ کاری سے تشکیل پاتی ہے جو وہ انسانوں پر کرتا ہے نہ کہ اُس سرمایہ کاری سے جو عمارتوں اور انفرا اسٹرکچر پرہوتی ہے۔(Human Capital is the Ultimate Investment )
ادارے ہوں، حکومتیں ہوں یا انسانوں کا کوئی بھی اجتماعی کام ہو، اس میں مرکزی اہمیت کام کرنے والے انسانوں اور ان کے اوصاف اور صلاحیتوں کی ہوتی ہے۔ کام یابی کا سب سے زیادہ انحصار ان ہی عوامل پر ہوتا ہے۔ اس لیے فطری طور پر سب سے زیادہ توجہ اور خرچ ان ہی پر ہونا چاہیے۔ انسانوں سے اور ان کی صلاحیتوں سے لاپروائی و بے نیازی اورعمارتوں اور انفرا اسٹرکچر پر زیادہ توجہ، ادارہ جاتی کاموں کی ناقص کارکردگی کا ایک بڑا سبب ہے۔ ابن خلدون ؒنے اپنےمقدمے میں ایک پوری فصل اسی موضوع پرباندھی ہے کہ عمارت سازی کا غیرمتوازن شوق کس طرح حکومتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔[26] اس کے نزدیک بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کے زوال کا ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی بجائے عالیشان عمارتیں، شان و شوکت اور چکاچوند ان کی توجہات کا مرکز بن جاتی ہیں۔
یہ عام مشاہدہ ہے کہ ایک ذہین اور کام یاب بزنس مین کوئی نئی کمپنی شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اچھے قابل افراد کو اچھی تنخواہ دے کر جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کمپنی ترقی کرکے ایک مقام پر پہنچتی ہے تو پہلے کرائے کی بلڈنگ میں، اچھے کمپیوٹر، مشینیں وغیرہ خریدتاہے، پھر اسٹاف کی سہولت کے لیے اے سی وغیرہ لگاتا ہے۔ عمارت کی تعمیر کا کام ترقی کے آخری مرحلے میں اس وقت ہوتا ہے، جب کمپنی بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اداروں میں بھی ترجیحات اور خرچ کے فطری مراحل یہی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اکثر ادارے بالکل الٹی ترتیب سے چلتے ہیں۔ ابتدا ہی بلڈنگ کی تعمیر سے ہوتی ہے۔ اور پیسہ آتا ہے تو قالینوں، ایرکنڈیشنوں اور گاڑیوں کا مرحلہ آتا ہے اور اسٹاف، اس کی تنخواہ اور سہولتیں سرے سے ترجیحی ترتیب میں کوئی جگہ ہی نہیں لے پاتی ہیں۔ اس الٹی ترتیب کی وجہ سے ادارے اعلیٰ کوالٹی کی صلاحیتوں سے محروم رہتے ہیں۔ عمارتیں عالیشان ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر کام کرنے والوں کی صلاحیتیں بہت معمولی ہوتی ہیں۔ یہ الٹی ترتیب اکثر اداروں کی ناکامی کا ایک بڑا سبب بنتی ہے۔ عمارتیں اور انفرا اسٹرکچر سفید ہاتھی ہوتے ہیں۔ صرف تعمیر پر ہی وسائل خرچ نہیں ہوتے بلکہ بعد میں ان کی نگہداشت اور استعمال بھی خاصی توانائی اور وسائل چاہتے ہیں۔ قبل ازوقت کھڑا کیا جانے والا انفرا اسٹرکچر، ادارے کے سارے وسائل کو اپنی نگہداشت کے لیے کھینچنے لگتا ہے اور انسانی وسائل پر یعنی اسٹاف کی تنخواہوں، ان کی ٹریننگ، کارکردگی میں اضافہ capacity building ماہرانہ مشاورت وغیرہ پر نہ توجہ ہوپاتی ہے اور نہ خرچ کرنے کے لیے وسائل بچتے ہیں۔
ادارے کے ارتقا کا لائف سائیکل بھی وہی ہونا چاہیے جو بزنس کا ہوتا ہے۔ اصل خرچ افراد پر ہو۔ باصلاحیت افراد کے ذریعے ادارہ بتدریج خود کفالت کی طرف بڑھے اور اپنے اندرونی وسائل سے عمارت سازی اور انفرا اسٹرکچر کی تعمیر کا کام کرے۔ یہ طریقہ ہی ڈیولپمنٹ کا فطری طریقہ ہے اور اس طریقے سے ترقی پانے والے ادارے ہی صحیح معنوں میں انسٹی ٹیوشن بن پاتے ہیں۔
وقف کی اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اہل ثروت کے عطیات عام طورپرایسے مستقل اثاثہ جات کے لیے ہوتے تھے جن سے فلاحی کاموں کے لیے مستقل آمدنی کا انتظام ہوسکے۔ یہی رجحان آج بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عطیات سے روز مرہ کے اخراجات کی تکمیل یا عمارتوں وغیرہ کی تعمیر کا کام کم سے کم ہو، ان سے ایسے اثاثہ جات بنیں جو آمدنی کے مستقل ذرائع پیدا کریں اور روز مرہ کے اخراجات ادارے کے اندرونی وسائل سے پورے ہوں اور ان میں تدریجاً ترقی ہو۔
تیسرا اصول:علم و تحقیق کی اساس پر اور ڈیٹا وتخصص کی مدد سے فیصلہ سازی ادارے کی لائف لائن ہے۔(Knowledge-Driven and Data supported Decisions are the lifeline of an institution)
یہ بہت اہم اصول ہے جو مسلمانوں کے اداروں میں بڑے پیمانے پر نظر انداز ہے۔علمی و تحقیقی مزاج پر ہم ان سطروں میں تفصیل سے کلام کرچکے ہیں۔[27] فیصلہ سازی، چاہے اس کا تعلق قیادتی عمل سے ہو یا انتظامی عمل سے، وہ تحقیق اور ریسرچ کی بھرپور کمک کے ساتھ اور ٹھوس معلومات، ڈیٹا، اسٹڈی رپورٹوں اور ماہرانہ مشوروں کی اساس پر ہو۔ یہاں ڈیٹا سے ہماری مراد صرف اعداد و شمار statisticsنہیں ہیں (اعداد و شمار کے اپنے مسائل ہیں) بلکہ ٹھوس معلومات اور حقائق ہیں جن سے اچھی طرح واقف ہوئے بغیر فیصلے کرنا اداروں کے لیے سمّ قاتل ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے اداروں میں ٹرسٹوں و سوسائٹیوں کی میٹنگوں سے پہلے رپورٹوں کی تیاری، ان کی پیشکش، ان پر مباحث، ڈیٹا اور اسٹڈی، آڈٹ، سروے وغیرہ کا رواج ہے۔ ان سب کاموں کو انجام دینے کے لیے مخصوص ادارے اور کمپنیاں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے اداروں میں ان سب کا رواج آج بھی بہت کم ہے۔ یا تو سرے سے ایسے مطالعات کرائے ہی نہیں جاتے اور اگر کہیں کرائے جاتے بھی ہیں تو انہیں وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو انہیں ملنی چاہیے۔ میٹنگ سے پہلے شرکائے میٹنگ کو جس گہرائی سے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان پر نوٹس لینے چاہئیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ سب رجحانات بالکل عنقا ہیں۔ فیصلے زیادہ تر وجدانی اور وقتی arbitrary ہوتے ہیں۔ میٹنگوں میں شرکا کے ذہنوں میں، محض اتفاق سے، جو خیالات وجدانی طریقوں سے آجائیں، بس وہی فیصلہ سازی کی اساس بنتے ہیں۔ ایسے وجدانی اور وقتی فیصلوں سے ادارے کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کرسکتے۔
چوتھا اصول:ندرت و تخلیقیت مسابقتی برتری کی اساس ہیں۔(Innovation and Creativity are the bedrock of competitive advantage)
اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اداروں کے مقابلے میں آپ کا ادارہ اس وقت زیادہ کام یاب ہوگا جب دوسروں سے زیادہ آپ کے پاس نئے آئیڈیا، نئے سولوشن اور اختراعی تدابیر ہوں گی۔ اس سلسلہ مضامین میں اسلامی تاریخ کے روشن ادوار کے جن اداروں کی ہم مثالیں پیش کررہے ہیں ان سب کی مشترک خصوصیت یہ تھی کہ وہ سب اپنے عہد سے بہت آگے تھے۔ بالکل انوکھے، نئے اور اپنے زمانے کے لیے نامانوس لیکن حد درجہ موًثر طریقے انہوں نے ایجاد کیے تھے اور اسی وجہ سے اسلامی طریقوں کا امتیاز دنیا پرواضح کرنے کا اور اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بن گئے تھے۔
جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد
ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ
اسلامی اوقاف کی جو مثالیں ہم پیش کرچکے ہیں وہ سب کی سب حیران کردینےکی حد تک اختراعی اور انوکھی تدابیر تھیں۔ اس مزاج کو مسلمانوں میں خود اسلام نے پروان چڑھایا تھا۔ اجتہاد کا اسلامی تصور ایک انقلابی تصور ہے۔ اجتہاد کا مطلب صرف فقہی اجتہاد نہیں ہے بلکہ کام کے نئے طریقوں کی کھوج، مسائل کے انوکھے حل کی تلاش اور نئے راستوں کی جستجو بھی ایک طرح کا اجتہاد ہے۔ اداروں کو اس کی قدم قدم پر ضرورت درپیش ہوتی ہے۔
تبدیلی و ندرت سے خوف اور بیزاری کی کیفیت اداروں کے زوال سے دوچار ہوجانے کے اہم اسباب میں شامل ہے۔ زوال پذیر اداروں کی کم زوری ہوتی ہے کہ وہ علانیہ تبدیلی کے مخالف نہ بھی ہوں تو عملاً نئی راہوں اور نئے خیالات و طریقوں کا خیرمقدم نہیں کرتے۔ مانوس روایات اور اطوار سے ہٹ کر سوچنا اور عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی تبدیلی یا ندرت کے لیے نظری طور پر آمادہ بھی ہوجائیں تو ان کی اجتماعی طبیعت اس تبدیلی کو عملاً قبول نہیں کرپاتی۔ ان کے افراد تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھال نہیں پاتے۔ جدید ونادر فیصلے کاغذ کی زینت بنے رہ جاتے ہیں عملی شکل نہیں لے پاتے۔
اختراع و ندرت کی اہمیت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اداروں کو سخت مسابقت کا سامنا ہو۔ وہ ایسی قدروں اور مقاصد کے علم بردار ہوں جن کا دنیا میں عام چلن نہ ہو اور اس وجہ سے بااثر قوتیں ان کو اپنا حریف سمجھتی ہوں۔ اسلام پسند اداروں کو زندگی کے ہر شعبے میں ایسی ہی مسابقت اور سخت گیر مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ ان حالات میں اختراع و ندرت کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے حالات میں لگے بندھے طریقے کام نہیں آتے۔ اگرلیڈرشپ کے اندر نئے حل تلاش کرنے اور ان کو نافذ کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو ادارے پیچھے رہ جاتے ہیں اور زمانہ آگے بڑھ جاتا ہے۔
اداروں میں ایجاد و اختراع اور نئے مفید تر طریقے اختیار کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تخلیقیت Creativity یعنی کام کرنے کے انوکھے اور نئے طریقے پیدا کرنے کی صلاحیت، مسائل کے بالکل انوکھے حل ڈھونڈنے کی صلاحیت اور دوسرے جوکھم لینے کی صلاحیت (Risk Taking)۔تحریک کو اس حوالے سے بھی اپنے اداروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بھی اصلاً قیادتی عمل کا حصہ ہے۔ اداروں میں ایجاد و اختراع کے موضوع کو ہم الگ سے تفصیلاً زیر بحث لائیں گے۔
پانچواں اصول: زیادہ سے زیادہ شورائیت ادارہ جاتی کام کا ایک اہم اساسی اصول ہے۔[28] (Maximum consultation is foundational principle of sound institutionalism)
ادارے اسی وقت صحیح معنوں میں ادارے بنتے ہیں جب اس کے ارکان، اسٹاف اور دیگر متعلقینstake holders ایک ٹیم بن کر کام کریں اور فیصلہ سازی، ان کے درمیان زیادہ سے زیادہ مشاورت کے ذریعے ہو۔ یہ بھی عین اسلامی اصول ہے۔ شورائیت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے دستوری تقاضے پورے کیے جائیں۔ جو مجالس ادارے کے دستور کے مطابق جن فیصلوں کی مجاز ہیں وہ پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ، بغیر کسی مداخلت کے آزادانہ فیصلے کرسکیں۔ ان پر نہ کوئی بیرونی دباؤ ہو اور نہ صدر سکریٹری وغیرہ ذمے داروں کی شخصیتیں ان مجالس کے اختیارات میں حارج ہوں۔ لیکن یہ بھی محض پہلا مر حلہ ہے۔ شورائیت محض تنظیمی ضابطے کا نام نہیں، ایک مزاج کا نام ہے۔ اس کا مطلب صرف ضابطے اور قانون کے مطابق چند رسمی مجالس کی تکمیل نہیں ہے۔ ضابطہ اور قانون تو غلط رویوں سے بچانے کا آخری چارہ ہوتے ہیں۔ اصلاً مزاج مطلوب ہے۔ اس مزاج کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ فیصلے کرنے میں صاحب اختیار یہ لحاظ رکھے کہ فیصلے محض اختیار کے ڈنڈے سے نہ ہوں بلکہ دلائل کی بنیاد پر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مشورے اور ان کے اعتماد سے ہوں۔ شورائیت دراصل دو طرح کے مشوروں کا نام ہے۔ ماہرین سے مشورہ اور جن لوگوں کا معاملہ سے تعلق ہے Stake Holders، ان سے یا ان کے نمائندوں سے مشورہ۔ یہ دونوں ہی تقاضے پورے ہونے چاہئیں۔
چھٹا اصول: معیار اور کمال کی طرف پیش قدمی کا راز مسلسل فیڈ بیک اور آڈٹ میں پوشیدہ ہے۔ (The secret of improvement and excellence is continuous feedback and audit)
معیاری ادارے اپنے استفادہ کنندگان سے، اسٹاف کے ارکان سے اور دیگر متعلقین سے مسلسل فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں۔ ہر خدمت کے بعد پوچھتے ہیں کہ ان کی خدمت کیسی رہی؟ اور اس میں مزید بہتری کے لیے کیا کیا جاسکتا ہے۔ کاروباری اداروں کی جانب سے تو فیڈ بیک کے لیے بار بار اصرار کیا جاتا ہے۔ رفاہی ادارے بھی لوگوں سے مسلسل فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے اداروں میں اس کا رجحان بھی بہت کم ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس رجحان کو فروغ دیا جائے۔
ساتواں اصول:اداروں کی بقا و تسلسل کا راز صحیح افراد اور جانشینوں کی مسلسل اور منصوبہ بند تیاری میں ہے۔(Succession planning is a cornerstone of organizational longevity and responsible leadership)
مسلمانوں کے متعدد اداروں میں یہ عام مرض ہے کہ قیادتوں اور انتظام میں نسلیں بدلتی نہیں ہیں۔ قیادتیں جس وژن اور اقدار کے ساتھ کام شروع کرتی ہیں، ان کی اساس پر کم عمر نوجوانوں کو تیار کرنے کی کوئی فکر ان کے اندر نہیں پائی جاتی۔ انتظامیہ میں جو ماہرین ابتدا میں میسر آجاتے ہیں، ان کے نئے جانشین تیار کرنے کی کوئی سنجیدہ اور منظم کوشش نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ اداروں کا ماضی تو شاندار ہوتا ہے، لیکن حال پریشان کن اور مستقبل یقینی طور پر تباہ کن نظر آنے لگتا ہے۔ بعض اداروں میں نسلی تسلسل (generational transfer)ہے تو وہ موروثیت کی اساس پر ہے۔ بانی یا منتظم کے فرزند ارجمند ہی جانشین بن کر سامنے آتے ہیں۔ اب تو تجارتی کمپنیوں میں بھی اس طرح کی موروثی جانشینی کو نقصان دہ سمجھا جانے لگا ہے۔
آئیڈیل ادارہ وہ ہے جس کی انتظامیہ میں نوجوانوں کی ایک قابل لحاظ تعداد ہو جو اپنے تجربے کار بزرگوں کی موجودگی ہی میں تسلسل کے ساتھ ادارے کے اصل مقصد و وژن اور اقدار سے ہم آہنگ ہوجائے۔ ہر رول اور ہر کلیدی ذمے داری کے لیے جانشین موجود ہوں۔ یہ فکر مندی اور اس کی کوشش بھی قیادت کی اہم ذمے داری ہے۔
ہمارے خیال میں اداروں کی جو بحث ہم نے اب تک کی ہے اور آئندہ قسطوں میں بھی کریں گے وہ اسی وقت کارگر ہوگی جب اداروں کے انتظامی اور قیادتی امور میں ان ضروری خصوصیات کی افزائش پر توجہ دی جائے گی۔ اس کے لیے ایک بڑی ثقافتی تبدیلی (cultural change) درکار ہے۔ یعنی صرف فیصلے درست کرنا کافی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے مزاج، سوچ، تنظیمی ماحول میں برسوں سے رائج روایات، ان سب کو بدلنے کی صبر آزما کوشش مطلوب ہے۔ یہ نہ ہو تو اداروں کا وہ کردار ممکن نہیں ہے جو اس سلسلہ مضامین میں زیر بحث ہے اورجس کے بغیر ادارے تحریک کے لیے اثاثہ بننے کی بجائے بوجھ (liability)بن جاتے ہیں۔
حواشی و حوالہ جات
[1] اس کي ايک جھلک کے ليے ملاحظہ ہو:
Mary Conway Dato-on, W. Glenn Rowe Ed.Introduction to Nonprofit Management: Text and Cases. United Kingdom: SAGE Publications, 2013.
[2] ادارہ جاتي سوچ کو گہرائي سے سمجھنے کے ليے:
Smith, Gordon T.. Institutional Intelligence: How to Build an Effective Organization. United States: InterVarsity Press, 2017.
[3] Heclo, Hugh. On Thinking Institutionally. United Kingdom: OUP USA, 2011.
[4] ibid
[5] احمد فوأد باشا وغيرهم؛ الموسسة في الاسلام: تاريخا وتأ صيلا؛ المعهد العالمي للفكر الاسلامي؛ الولايات المتحده الامريكية؛ ص 44-111
[6] حوالہ سابق ص 53-72
[7] حوالہ سابق؛ ص80-92
[8] شبلي نعماني؛ الفاروق؛ حصہ دوم؛ مطبع معارف؛ اعظم گڈھ؛ ص 299-302
[9] سيد سعادت اللہ حسيني؛ وقف: اسلامي ادارہ سازي کا تاريخي ماڈل (اشارات)؛ زندگي نو؛ فروري 2025
[10] مولانا مودوديؒ کے تنظيمي کارنامے پر ايک اہم قابل مطالعہ مضمون
حسن صہيب مراد؛ مولانا مودودي کا تنظيمي کارنامہ؛ ماہنامہ ترجمان القرآن؛ لاہور، مئي 2004
[11] Kotter, J. P. A Force for Change: How Leadership Differs from Management. New York: Free Press(1990)p 4
[12] Zaleznik, A. (1998). Managers and Leaders: Are They Different? Harvard Business Review, 55(5), 67-78
[13] ibid
[14] Yukl, Gary (2006), sixth edition, ”Leadership in organizations”, Prentice Hall, New Jersey.page 5
[15] ابن خلدون؛ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر؛ دار الفكر، بيروت؛ 1981؛ ص273
[16] Kotter, J. P. A Force for Change: How Leadership Differs from Management. New York: Free Press(1990)
[17] ibid
[18] Peter F. Drucker ; Management: Tasks, Responsibilities, Practices; Harper & Row, New York.1974;Page 45.
[19] Bennis, Warren., Nanus, Burt. Leaders: The Strategies for Taking Charge. United States: HarperCollins, 2012.
[20] ibid
[21] Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
[22] Bennis, W., & Nanus, B. (1985). Leaders: The Strategies for Taking Charge. New York: Harper & Row, p. 21
[23] Ibid p. 22.
[24] Northouse, P. G. (2019). Leadership: Theory and Practice (8th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, p. 164.
[25] Drucker, P. F. (1993). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: HarperBusiness, p. 381.
[26] ابن خلدون؛مقدمة ابن خلدون؛ الجزء الثاني؛ دارالبلخي؛ دمشق؛ ص 29
[27] سيد سعادت اللہ حسيني؛ علمي ترقي اور تمکين امت؛ (اشارات)؛ زندگي نو،اپريل 2023
[28] Conger, J. A., & Fulmer, R. M. (2003). Developing Your Leadership Pipeline. Harvard Business Review, 81(12), 76-84, p. 78