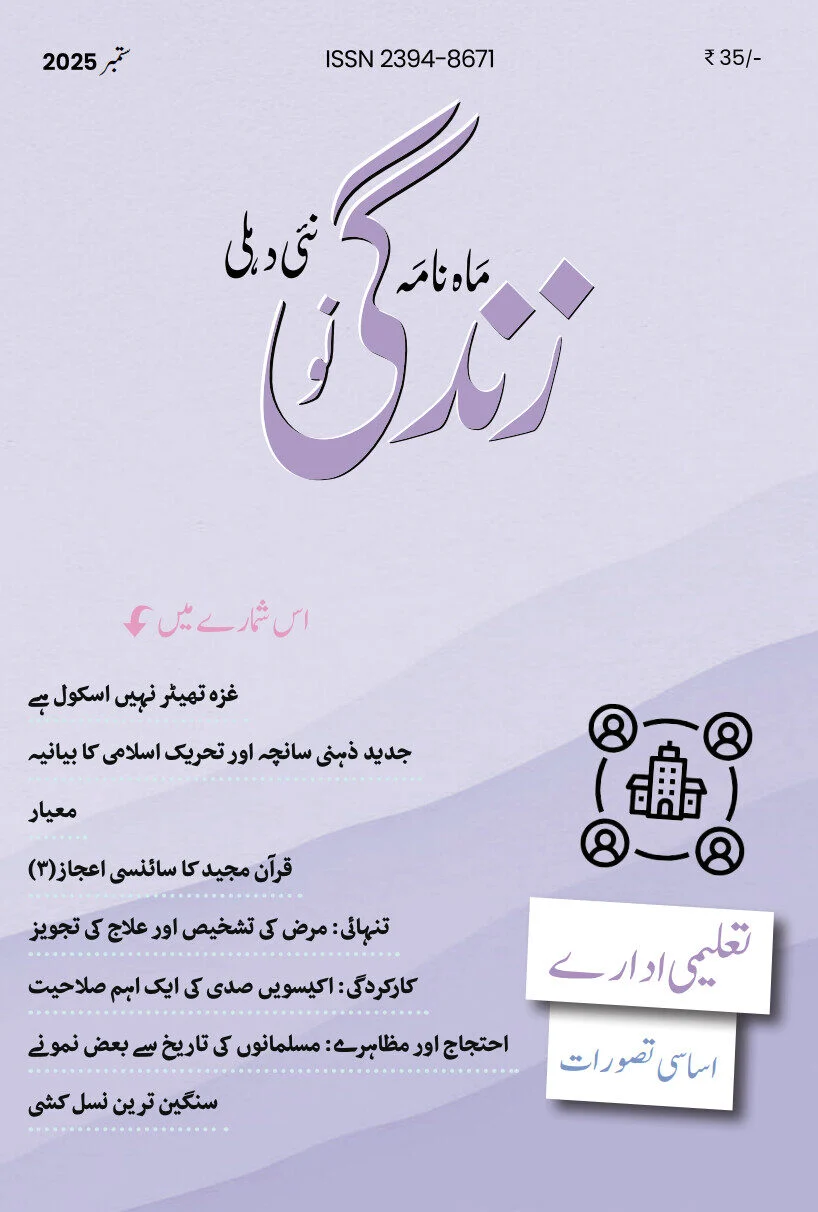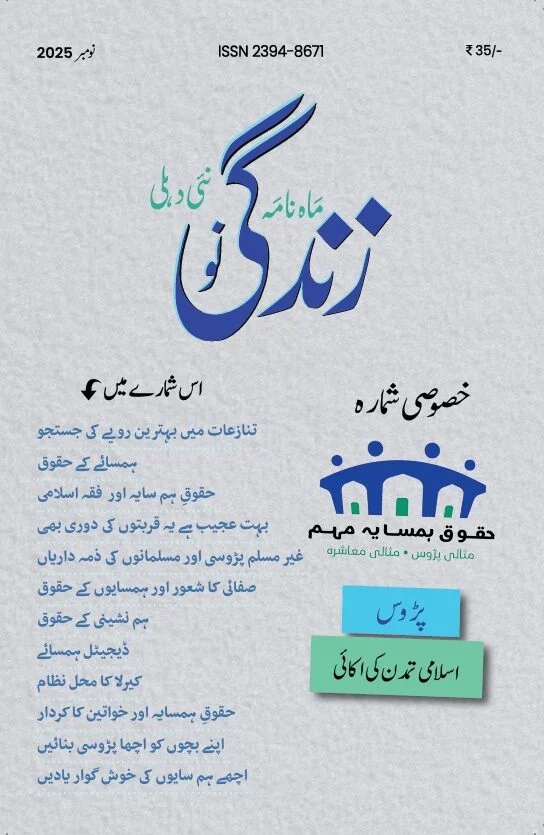ہردورکا ایک مخصوص ذہنی سانچہ ہوتا ہے جو اس دور کے لوگوں کی سوچ اور رجحان کو ایک مخصوص رخ دیتا ہے۔ ماضی میں انسان توہمات کے زیر اثر تھا، جس سے مذہب کی اصل تعلیمات چھپ گئی تھیں۔ توہمات کے دور میں ہر واقعے اور حیات و کائنات کے مختلف مظاہر کی غیر معقول توہماتی توجیہ قابل قبول بن جاتی تھی۔ اس طرح کے ماحول میں انبیائے کرام علیہم السلام خدائی معجزات کے ذریعے توہماتی فریب اور معاشرتی ظلم و فساد کی بیخ کنی کرتے اور لوگوں کو معقولیت اور ہدایت الہی کی راہ دکھاتے رہے۔ لیکن بعد میں بااثر طبقات اپنے مفادات کے لیے مذہب کے ہی نام پر ایسا توہماتی تانا بانا بنتے رہے کہ جس سے اصل مذہب کچھ رسومات اور بالادست طبقے کے مفادات تک محدود ہو جاتا۔ یہ صورت حال ہندوستان کے ورن آشرم اور یورپ کے کلیسائی نظام کی صورت میں صدیوں تک برقرار رہی ہے۔ تاہم اس دور تنزل میں بھی جہاں تک ذہنی سانچے کا تعلق ہے وہ مذہبی رہا اور خدا کے انکار کا رجحان غالب رجحان نہ بن سکا۔ لیکن یوروپی نشاہ ثانیہ کے بعد بتدریج مغرب میں عقل کی خود مختاری اور چرچ کے اثر سے آزادی کے رجحان نے ذہنی سانچہ کو سیکولر بنیادوں پر استوار کر دیا۔ سترہویں سے بیسویں صدی تک مغربی معاشرے میں مذہبی طرز فکر اور رجحان کی جگہ سیکولر طرز فکر اور رجحان نے لے لی۔ اب انسانی عقل کو سب سے برتر اور ہدایت الہی سے بے نیاز سمجھا جانے لگا۔ اس دور میں مغرب ترقی کر رہا تھا جب کہ مشرق زوال کا شکار تھا، اس لیے مشرقی ذہن مغربی افکار و نظریات کے سامنے مغلوب ہوتا چلا گیا۔ یہی دور ہے جب مغربی عقل نے سیکولر نظریہ سازی کے ذریعے انسانی زندگی کے گوناں گوں معاملات و مسائل کو سلجھانے کی کوششوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مغربی افکار و نظریات نے عالمی سطح پر جدید سیکولر نظام کی داغ بیل ڈالی۔ مغرب کی سائنسی اور صنعتی ترقی نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور اس ترقی کے جلو میں مغربی سیکولر نظریات کو پذیرائی حاصل ہوئی۔
اس پس منظر میں اسلامی تحریکوں نے اسلام کو ایک نظریے اور نظام حیات کے پیراہن میں پیش کیا۔ لیکن اس نئے انداز پیش کش کے باوجود، اسلام کو اشتراکی یا سرمایہ دارانہ نظام کی طرح لوگوں کے لیے بلاتفریق مذہب و ملت قابل قبول بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظریہ حیات اور نظام زندگی، دیگر سیکولر نظریات کی طرح محض ایک نظریہ یا نظام نہیں ہے جو مذہبی شناخت سے خالی ہو۔ اسلام نظریہ و نظام حیات بھی ہے اور مذہب بھی ہے جوعقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی زندگی سب کو محیط ہے۔ اسی جامعیت اور ہمہ گیری کی وجہ سے اسلام کو صرف ایک نظریاتی یا سیاسی یا معاشی نظام کے طور پر دوسرے مذاہب والوں کے لیے قابل قبول بنانا ممکن نہیں ہے۔ یہی خصوصیت اسلام کو دیگر نظریات اور نظاموں سے الگ کرتی ہے۔ تاہم اسلامی نظام حیات کے مختلف پہلوؤں کے کام یاب تجربات اگر عامة الناس کے لیے مفید ثابت کیے جاسکیں تو توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنے سماجی، معاشی، سیاسی مسائل کو حل کرنے میں اسلامی اصول و نظام سے اخذ و استفادہ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ ماضی میں بھی اسلام کے اخلاقی، خاندانی اور روحانی پہلوؤں نے دیگر اقوام کو متاثر کیا ہے۔ اسلام کی نظریاتی سادگی اور عقل عامہ سے مطابقت دیگر مذہبی بیانیوں کے مقابلے میں جدید ذہن کو سیکولر اور الحادی خلجان سے نجات دلا سکتی ہے۔
نظریے اور نظام کا جدلیاتی پس منظر
نظریہ (Ideology) دورجدید کی اصطلاح ہے جسے سب سے پہلے فرانسیسی فلسفی ٹریسی نے اٹھارویں صدی کے آخر میں استعمال کیا تھا۔ ٹریسی نے اس لفظ کو افکار و تصورات کے علم کے طور پر متعارف کروایا۔ انیسویں اور بیسویں صدی میں یہ اصطلاح تصورِ حیات کے معنوں میں استعمال ہونے لگی۔ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے اس کو ایک جامع نظامِ فکر قرار دیا جو سیاسی، معاشی اور سماجی تحریکوں کو جنم دیتا ہے۔ مارکسی مفکرین کے مطابق نظریہ دراصل حکمراں طبقے کے مفادات کی نمائندگی کرتا ہے اور طاقت و غلبے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بیسویں صدی میں اس لفظ کا استعمال وسیع ہو گیا اور اسے مختلف عالمی نظریات جیسے لبرل ازم، سوشلزم اور فاشزم کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ خود مارکسی مفکرین بھی اپنے افکار و خیالات کو نظریے کے طور پر پیش کرنے لگے۔ لیکن انھوں نے مارکسی نظریات کو سائنسی نظریہ قرار دیا جو معاشی، سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کی وضاحت اٹل قانون فطرت کے طور پر کرتا ہے۔ اس طرح نظریہ کی اصطلاح اپنےغیر جانب دار یا مثبت معنی سے نکل کر جدلیاتی صورت اختیار کر گئی۔ مجموعی طور پر، نظریہ کو کبھی سماجی اصلاح اور شعور کے فروغ کا، اور کبھی سماجی تسلط اور حقیقت کی پردہ پوشی کا آلہ سمجھا گیا۔ آج بھی نظریات کے سماجی کردار اور ان کی حقیقت پر بحث جاری ہے۔ نظریہ دراصل خیالات، اقدار اور عقائد کا ایک منظم مجموعہ ہوتا ہے جو دنیا کو سمجھنے اور فیصلے کرنے میں رہ نمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک مضبوط نظریہ منطقی اور مربوط ہوتا ہے، سماجی، سیاسی یا معاشی حقائق کی وضاحت کرتا ہے، اور سماجی و سیاسی تبدیلی کے لیے پروگرام فراہم کرتا ہے۔ اس سے گروہی شناخت بنتی ہے اور حلیف و مخالف کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔
برطانوی فلسفی مائیکل فریڈن (Michael Freeden)نے نظریات کی تشکیل و جدلیات پر گہری بحث کی ہے۔ ہر نظریہ چند “بنیادی” تصورات و اقدار پر مشتمل ہوتا ہے جو عام طور پرآفاقی ہوتے ہیں، جیسے مساوات، عدل، آزادی، وغیرہ۔ ان بنیادی تصورات کے علاوہ کچھ ثانوی تصورات بھی ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، یا دیگر نظریات سے مستعار لیے جا سکتے ہیں، جیسے رواداری، نظم، یکجہتی، ترقی، وغیرہ۔ ایک ہی تصور جیسے “آزادی” یا “مساوات” مختلف نظریاتی سیاق و سباق میں مختلف معانی رکھ سکتا ہے۔ نظریات مسلسل “تصوری مقابلے” (conceptual competition) میں مصروف ہوتے ہیں۔ نظریہ بنیادی و آفاقی تصورات کا حتمی معنی متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ایک نظریہ دراصل دوسرے نظریے کی تشریح کو مسترد کرتا ہے۔ نظریات اپنے متعین تصورات کو متفق علیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنی تشریح کے ذریعے ابہام و تضاد کو دور کرتے ہیں تاکہ داخلی سطح پر فکری اتحاد برقرار رہے اور بیرونی چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ مقابلہ نہ صرف مختلف نظریات کے درمیان بلکہ ایک ہی نظریے کے مختلف فکری دھاروں کے درمیان بھی ہوتا ہے، مثلاً لبرل ازم یا سوشل ازم یا اسلامی تحریکوں کے مختلف مناہج فکر کے مابین بحث و نزاع۔ نظریات کی نشوونما نہ صرف بیرونی چیلنجوں سے بلکہ حامیوں اور تنقید کرنے والوں کے درمیان جاری تعبیر و تفہیم اور مذاکرات سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ جو نظریہ اپنی تشریح کو معقول و مقبول بنا کر دوسری نظریاتی تعبیر کو حاشیے پر ڈال دیتا ہے، وہ کام یاب ہو جاتا ہے۔ چناں چہ نظریاتی کشمکش میں عوامی تائید اسے ملتی ہے جو بنیادی وآفاقی تصورات جیسے آزادی، مساوات، عدل، وغیرہ کے بارے میں اپنی نظریاتی تعبیر کوغالب رجحان بنانے میں کام یاب ہوجاتا ہے۔
آئیڈیالوجی کے جدید تصور سے پہلے، مسلم معاشرے میں ایمان، عقیدہ، شریعت، دین، اخلاق، تزکیہ، رسوم، وغیرہ جیسی اصطلاحات کا چلن عام تھا جو مذہبی علمیات (epistemology) میں استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ اصطلاحات زیادہ تر انسانی زندگی کے تعبدی، اخلاقی یا روحانی پہلوؤں کو اجاگر کرتی تھیں۔ اسلامی تہذیب میں سیاست کے لیے خلافت، بیعت اور شوریٰ، معیشت کے لیے زکوٰة، خمس، جزیہ، قرضِ حسن وغیرہ جب کہ سماجی حرکیات کے لیے عصبیت، اخوت،عدل اوراحسان جیسی اصطلاحات استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ اصطلاحات نہ صرف اس دور کے اداروں و روابط کی وضاحت کرتی تھیں بلکہ اس وقت کے معاشرتی ڈھانچے اور دینی نقطہ نظر کو بھی نمایاں کرتی تھیں۔ آئیڈیالوجی (ideology) اور نظام (system) کی اصطلاحات کے استعمال کا پس منظر مغربی معاشرے کا دور عقلیت ہے جس میں انسانی عقل کو وہی مقام حاصل ہے جو مذہبی دور میں الہام و وحی کو حاصل تھا۔ دراصل آئیڈیالوجی اور نظام کے الفاظ سیکولر اصطلاح کے طور پر معروف ہوئے جو مذہبی عنصر سے مبرا تھے۔
سیکولر نظریات اور مسلم مفکرین
بیسویں صدی میں جدید دور کے سیکولر ذہنی سانچے کو توڑنے اور اس کی جگہ ہدایت الہی پر مبنی فکر و نظر کو راسخ کرنے کے لیے ایک منظم کوشش کا آغاز ہوا، جسے ہم تحریک اسلامی کے جامع عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ تحریک اسلامی نے آئیڈیالوجی اور نظام جیسی سیکولر اصطلاحات کو اسلام کے ہمہ گیر پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس طرح جدید ذہن جو سیکولر اصطلاحات سے مانوس تھا اس پر اسلام کی عصری معنویت آشکار ہوئی۔ حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق، تحریک اسلامی کے مفکرین نے سیکولر نظریات اور نظام کے مقابلے میں ہدایت الہی کو جدید انداز و استدلال کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس پس منظر میں تحریکی مفکرین نے اسلام کو ایک مربوط نظریے اور نظام حیات کی صورت میں پیش کیا، تاکہ جدید ذہن دین سے مانوس و مطمئن ہو کر اس کے قیام کی جدوجہد میں شریک ہو۔
بیسویں صدی کے نصف اول میں مسلم علما، جدید مسلم دانش وروں اور تحریک اسلامی کے مفکرین نے نیشنلزم، سیکولرزم، حاکمیتِ الٰہ، حاکمیتِ جمہور، طاغوت اور جاہلیتِ جدیدہ جیسے تصورات و نظریات پر گہرے اور متنوع علمی بیانیے پیش کیے۔ ان کا بیانیہ بنیادی طور پر اسلامی اصولوں کی معقولیت، مغربی نظریات کی تنقید اور اسلامی فکر و نظر کی تجدید پر مرکوز تھا۔ مسلم مفکرین نے سیکولرزم کو کفر اور دہریت قرار دیا، کیوں کہ یہ خدا کی حاکمیت کو رد کرتا ہے اور انسانی معاشرے کو الٰہی ہدایت سے جدا کرتا ہے۔ خلافتِ عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، سیکولرزم کو اسلام دشمن اور مسلمانوں کے لیے خطرہ سمجھا گیا جس کا اظہار اتاترک کمال پاشا کے اقدامات سے نمایاں طور پر ہو رہا تھا۔ تاہم، بعض جدید دانش وروں نے سیکولرزم کے چیلنج کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا اسلامی تناظر میں تجزیہ کیا اور اس کے الحادی پہلو کو رد کرتے ہوئے اسلام سے مطابقت کو اجاگر کیا۔
مسلم مفکرین نے قوم پرستی (نیشنلزم) کی قوت کو بھی رد و قبول کے ساتھ برتنے کی کوشش کی۔ ایک طرف انھوں نے نوآبادیاتی ظلم کے خلاف خودمختاری کے لیے کی جانے والی قوم پرستانہ جدوجہد کی حمایت کی، مگر دوسری طرف اس بات پر زور دیا کہ امت کی تشکیل نسل یا وطن کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ عقیدہ توحید پر ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلم قومی حکومت کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے کیوں کہ حاکمیت صرف خدا کی ہے اور انسانی حکومت خواہ مسلمانوں کی ہی کیوں نہ ہو اسے ہدایت الہی اور شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ جمہوری نظام (حاکمیتِ جمہور) کو بعض دانش وروں نے انسانی فطرت کے مطابق ایک مثبت رجحان تو قرار دیا، لیکن اس کو الٰہی ہدایت کے تابع رکھنے پر زور دیا۔ مسلم مفکرین نے طاغوت کو ہر اس غیر الٰہی اور ظالمانہ طاقت کے طور پر شناخت کیا جو مسلمانوں کی آزادی اور دین کی حفاظت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس ساری صورت حال میں اصلاحی اور تجدیدی تحریکیں بھی ابھریں، جن کا مقصد جدید علوم اور سائنس کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا اور ہمہ گیر تبدیلی کی تحریک بھی پیدا ہوئی۔ تحریک اسلامی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے جدید سیکولر ذہنی شاکلے ( (secular mindset کو نظریاتی طور پر چیلنج کرتے ہوئے اسلامی نظریے اور نظام حیات کو عصری اسلوب میں پیش کرنے اور سماجی تبدیلی کے لیے ایک منظم جدوجہد کا آغاز کیا۔
تحریک اسلامی کے نزدیک سیکولرزم، نیشنلزم اور سیکولر جمہوریت (حاکمیتِ جمہور) بنیادی طور پر اسلامی عقائد، وحدت امت اور اللہ کی حاکمیت سے متصادم ہیں۔ تحریک نے اپنے دلائل کی عمارت قرآن و سنت، اسلامی تاریخ اور عقلی تجزیے پر استوار کی۔ تحریک نے واضح کیا کہ مغربی افکار و نظریات مسلم معاشرے کے اصول و اقدار سے متصادم ہیں۔ قرآن مجید میں طاغوت سے اجتناب اور اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا [سورہ النساء: 60]۔ مولانا مودودیؒ نے اپنی تصانیف میں مغربی تہذیب، سیکولرزم، سرمایہ داری، سوشلزم اور لبرلزم کو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ چناں چہ جماعت اسلامی نے ابتدا میں سیکولر جمہوریت، فاشزم، سرمایہ داری اور سوشلسٹ نظام کو جاہلیت جدیدہ قرار دے کر ان سے علیحدگی، مقاطعہ اور رد و ابطال کی پالیسی اپنائی۔ جاہلیت جدیدہ سے مراد وہ جدید مغربی افکار و نظریات ہیں جو اسلامی عقائد و اقدار سے متصادم ہیں۔
سیکولر اور اسلامی تصورات میں فرق و مماثلت
جیسا کہ واضح کیا گیا کہ دور جدید میں اسلامی تحریک نے اسلام کو محض ایک مذہب نہیں بلکہ نظریہ زندگی اور مکمل نظامِ حیات کے طور پر پیش کیا۔ اس تحریک کا مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں انفرادی، اخلاقی، سماجی اور سیاسی تبدیلی کے لیے ایک منظم جدوجہد کو فروغ دینا ہے۔ اس زمانے میں کمیونزم اور سرمایہ دارانہ نظام کے بالمقابل اسلامی نظام کو ایک متبادل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اجتماعی معاملات میں ہدایت الہی سے بے نیازی کے رجحان کو رد کرتے ہوئے حاکمیت الٰہ (Divine Sovereignty) کا تصور اجاگر کیا گیا۔ اسی کے ساتھ حاکمیت جمہور کے تصور میں موجود جمہوری اصول و اقدار کو خلافت انسانی کے سانچے میں پیش کیا گیا۔
عوامی حاکمیت (Popular Sovereignty) کا تصور بادشاہت اور پاپائیت کے اقتدار کو چیلنج کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ریاست کی اصل طاقت اور قانونی حیثیت عوام کی رضا و مرضی سے وجود میں آتی ہے۔ حکومت اسی وقت جائز سمجھی جاتی ہے جب وہ عوام کی مرضی سے وجود پائے اور عوام کی مرضی کی نمائندگی کرے۔ اس تصور کی جڑیں قدیم زمانے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یونان کی شہری مملکت، رومن سلطنت اور قدیم ہندوستانی سیاسی فکر میں اس کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ جدید سیاسی فلسفے میں یہ نظریہ روسو کے افکار سے مقبول ہوا، جس نے اجتماعی ارادہ (General Will) کا تصور پیش کیا اور اقتدار اعلیٰ کو عوام کا حق قرار دیا۔ فرانسیسی انقلاب اور امریکی سیاسی نظام کی بنیاد بھی اسی اصول پر رکھی گئی۔
فلاسفہ اور دینی علما نے اس پر بحث کی ہے کہ آیا عوامی حاکمیت اور الٰہی حاکمیت ایک ساتھ چل سکتی ہیں یا نہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اگر لوگ اپنی مرضی سے الٰہی قانون کو قبول کریں تو دونوں میں اشتراک ممکن ہے۔ لیکن اکثر کا موقف یہ ہے کہ قانون کا منبع اگر انسانی مرضی کو تسلیم کر لیا جائے تو محض الٰہی حکم کے اتباع کی معنویت برقرار نہیں رہ سکتی۔ بلا شبہ عملًا تو ہدایت الہی کی اتباع انسانی ارادے پر ہی موقوف ہے لیکن اصولًا قانون کا منبع جب تک ہدایت الہی کو تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک وہ نظام مملکت غیر دینی نظام ہی کہا جائے گا خواہ قانون سازی ہدایت الہی کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔
عیسائی الہیات (Theology) میں حاکمیت کا غالب تصور خدا کی حاکمیت (God’s Sovereignty) پر ہی مبنی ہے، یعنی حتمی اختیار اور طاقت خدا کے پاس ہے اور وہی کائنات کا اصل حکم راں ہے۔ یہ تصور کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں روایات میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ عیسائی متکلمین خدا کی قدرتِ کاملہ (Omnipotence) اور اس کی حاکمیت (Sovereignty) میں فرق کرتے ہیں۔ قدرتِ الہ طاقت کی مکملیت یعنیtotality کا نام ہے، جب کہ حاکمیت الہ اس طاقت کو استعمال کرنے کا حق ہے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ خدا کی قدرت انسان کو آزادی دینے کے باوجود بھی برقرار رہتی ہے، یعنی کوئی بھی واقعہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تاہم، اس بات پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ خدا براہ راست کس حد تک کنٹرول کرتا ہے اور انسان کو کہاں تک آزاد چھوڑتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بحث مسلم متکلمین کے یہاں بھی پائی ہے جسے مشیت الہی اور ہدایت الہی کے مابین فرق کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے۔ مشیت الہی انسانی خواہش، ارادے یا مرضی کے تابع نہیں ہے جب کہ ہدایت الہی کی بجا آوری کا تعلق انسانی ارادے سے ہے۔
حاکمیت کے حوالے سے دوسری بحث معصومیت (Infallibility) سے متعلق ہے۔ عوامی حاکمیت کے تصور پر مبنی سیاسی اصولوں میں معصومیت (Infallibility) کو لازمی خصوصیت نہیں سمجھا جاتا ہے۔ جدید سیاسی نظام، خصوصاً آئینی جمہوریتیں، رائے عامہ کی غلطی کے امکان کو تسلیم کرتی ہیں۔ لیکن روسو کے اجتماعی ارادہ (General Will) کے تصور میں معصومیت کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ روسو کے نزدیک عوام کی مشترکہ مرضی بنیادی طور پر درست اور اجتماعی بھلائی کی ضامن ہے۔ کلاسیکی لبرل روایت میں عوامی حاکمیت کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی اتھارٹی عوام کی رضا مندی سے قائم ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عوامی فیصلے ہمیشہ درست یا معصوم ہوں۔ اس کے برعکس، عوامی فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، جس سے اکثریت کی آمریت جیسے خدشات جنم لیتے ہیں۔ اس لیے جدید جمہوری نظام میں مختلف تحفظاتی اقدامات اور قانونی تحدیدات (check and balance system) کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح، سترہویں سے بیسویں صدی تک کے نظریاتی ارتقا کے دوران عوامی اور الٰہی حاکمیت کی بحث اور معصومیت کے تصور نے جدید دنیا کے سیاسی و سماجی ڈھانچے کو گہرائی سے متاثر کیا ہے۔
روایتی مسلم علما، فقہا اور مفسرین نے بھی حاکمیت(sovereignty)کے بارے میں تفصیلی بحث کی ہے، لیکن ان کا زاویہ نظر مختلف رہا ہے۔ اسلامی تصورِ حاکمیت میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی اللہ ہی شارع اور مقتدر اعلی ہے۔ حلال و حرام، جائز و ناجائز اور صحیح و غلط قرار دینے کی حتمی اتھارٹی اللہ تعالٰی کی ہے۔ ریاست اور حکمراں (یا خلیفہ) اللہ تعالٰی کے صریح احکام و ممانعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ان کی ذمہ داری حکم الہی کا نفاذ اور ہدایت الہی کی روشنی میں بدلتے حالات میں عادلانہ قانون سازی اور امن و عدل کا قیام ہے۔ انھیں قانون سازی کا بلاتحدید اختیار (unrestricted power) نہیں ہے۔ امام ماوردی کے مطابق ریاست اور حکمراں کو اللہ کے احکام کے مطابق چلنا لازم ہے۔ حکمراں کو عوام کی رائے (شورائیت) سے منتخب ہونا چاہیے، مگر منتخب حکمراں کو بھی شریعت اور شورائیت کا پابند ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کے مطابق حکمراں عوام کی بھلائی اور شریعت کے نفاذ کا ذمہ دار ہے اور اگر وہ عدل سے ہٹے تو اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی۔ ابن خلدون نے معاشرتی نظم و نسق کے لیے حاکمیت کو ضروری قرار دیا ہے، مگر اس کی بنیاد بھی دینی اصولوں پر ہونی چاہیے۔ مولانا مودودیؒ نے حاکمیتِ الٰہ کا تصور پیش کرتے ہوئے جدید ریاستی نظام کے تناظر میں حاکمیت الہ، خلافت جمہور اور شورائیت کے بنیادی تقاضوں کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے مطابق انسان یا عوام کو قانون سازی کا حق صرف اس حد تک ہے جہاں وہ اللہ کی شریعت سے متصادم نہ ہو۔ اسلامی نظام ریاست میں شوریٰ (مشاورت) کے ذریعے عوامی رائے کو اہمیت دی جانی لازم ہے، لیکن یہ مکمل عوامی حاکمیت (popular sovereignty)نہیں ہے بلکہ حاکمیت الہ(divine sovereignty)کی پابند ہے اور یہ تصورخلافت کا لازمی عنصرہے۔
نظریہ، عملیت پسندی اور حکمت عملی
اگرچہ نظریات کسی تحریک کی بنیاد اور اس کے محرک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی نظریات ہمہ گیر تبدیلی کے لیے برپا کی گئی تحریکوں کو نئی صورت حال میں نئی حکمت عملی بنانے کے عمل میں الجھنوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ جب نظریات بدلتے ہوئے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات میں مطلوبہ منزل کے لیے نئے راستوں کی تلاش اور موجود امکانات کو بروئے کار لانے میں درپیش مسائل کو نہ سلجھا سکیں تو تحریکوں کو داخلی بحث و نزاع سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح کی نزاعی صورت حال کو جنم دینے میں دیگر عوامل بھی کارفرما ہو سکتے ہیں، مثلًا نظریاتی مداہنت، اخلاقی گراوٹ اور تخلیقی جمود۔ نظریاتی تحریکوں میں اندرونی سطح پر رفقائے تحریک کے درمیان فکری ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے مکالمے، مباحثے اور استدلال کے بجائے اگر روایت پسندی اور بے جان ضابطہ بندی کی مستقل بیساکھی کا سہارا لیا جانے لگے توآزادانہ سوچ بچار اور تازہ فکری کا رجحان کم زور پڑنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تحریک کے اندر بےاعتمادی اور شک کی فضا پروان چڑھتی ہے۔ بعض اوقات اس طرح کی صورت حال میں نظریاتی تحریکوں کے اندر شدت پسندی، انتہا پسندی یاٰ تشدد پسندی کے رجحانات بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف تحریک کا دائرۂ اثر مختصر ہونے لگتا ہے بلکہ منزل مقصود کی راہ بھی تنگ ہو جاتی ہے۔
نظریاتی بیانیے اور تصورات وقت اور مقام کے تغیر کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیوں کہ ان کا رشتہ سماجی، سیاسی، معاشی احوال سے وابستہ و پیوستہ ہوتا ہے۔ نظریات کا ظہورعام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے عہد کے حالات کو سمجھنے اور ان کے حل تک پہنچنے کی جستجو کرتا ہے۔ جیسے جیسے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے — خواہ وہ انقلاب ہو، سماجی تحریک ہو یا تمدنی تبدیلی ہو — نظریات بھی ان نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے لگتے ہیں۔ روشن خیالی (Enlightenment)کی مثال سامنے ہے۔ بادشاہت اور مذہبی بالادستی کے ردِ عمل میں عقل اور انفرادی حقوق پر زور دینے کی تحریک اٹھی اور بتدریج اس نے مذہبی انداز فکر اور سماجی رویے کو بدل ڈالا۔ اسی طرح صنعتی سرمایہ داری کے ابھرنے کے بعد سوشلزم اور کمیونزم جیسے نظریات نے معاشی نابرابری کو چیلنج کیا اور پرولتاریہ کی حکم رانی کا نظریہ ابھرا جس میں انفرادی ملکیت کے تصور کی جگہ اجتماعی ملکیت کے تصور کو جنم دیا۔
اسی طرح استعماری غلبے اور سیکولر طرزفکر کے خلاف مسلم مفکرین اور تحریکوں نے مسلم معاشرے میں ایک نئی بیداری کی داغ بیل ڈالی اور روایتی مذہبی جمود کو توڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ استعماریت کے خلاف اٹھنے والی قومی لہر نے اسلامی تحریکوں کے سامنے نظامِ باطل پر نظریاتی تنقید کی راہ کھولی۔ چناں چہ نظام باطل کو نظریاتی، دستوری اور عملی سطح پر چیلنج کیا گیا۔ اسلامی تحریکوں نے رائے عامہ کو ہم وار اور جمہوری ذرائع کو استعمال کرکے اسلامی نظام قائم کرنے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ جمہوری سوچ نے اسلامی تحریکوں کو پرامن، تدریجی اوراخلاقی جدوجہد پر ثابت قدم رکھا۔ اور انھیں خفیہ یا پرتشدد اقدامات سے دور رکھا۔ چناں چہ عام طور پر اسلامی تحریکوں نے جمہوریت، انسانی حقوق اور سماجی رواداری جیسے جدید تصورات کو اسلامی اقدار و اصول کی بنیادیں فراہم کیں۔ اس کی بنا پر اسلامی تحریکوں میں عدم تشدد اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا مزاج پختہ تر ہوا۔ وقت کے ساتھ اسلامی تحریکوں نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلیاں بھی کیں۔ کچھ نے سیاسی شرکت اور اشتراکِ عمل کی راہ اپنائی، جب کہ بعض نے خود کو صرف اصلاحی اور دعوتی سرگرمیوں تک محدود رکھا۔ جدید دور میں بعض اسلامی تحریکوں نے مغربی اورغیرمسلم اقوام کے ساتھ مکالمے اور مشترکہ مسائل کو حل کرنے میں اشتراک و تعاون کا طریقہ اختیار کیا۔ اسلامی تحریکوں کو اجتہاد و تجدید کی کوششوں پر روایتی حلقوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بتدریج مسلم معاشرے میں ایک نئی فکری ہلچل اورعصرحاضر کے سوالات پر اسلامی تناظر میں بحث و مباحثے کی لے زور پکڑتی چلی گئی۔
نظریاتی بیانیوں کو مؤثر اور حالات سے ہم آہنگ بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نظریات پر قائم رہتے ہوئے تخلیقی سوچ کے ساتھ نظریات کے اطلاقی پہلوؤں کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ فکری قائدین بنیادی اصول و نظریات کی نئی تشریحات پیش کرنے کی کوشش کریں۔ کام یاب تحریکیں اپنے پیغام اور حکمت عملی کو سماجی، سیاسی اور معاشی حالات کے مطابق ڈھالتی ہیں۔ مولانا مودودی نے تحریک اسلامی کے لائحہ عمل پر گفتگو کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ جماعت کے ابتدائی پروگرام میں یہ بات شامل ہے کہ ایک طرف جماعت کے افراد اپنی ذاتی اصلاح اور تزکیہ کی طرف متوجہ رہیں اور دوسری طرف رائے عامہ کو حاکمیتِ غیر اللہ کے انکار اور حاکمیتِ رب العالمین کو قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اس راہ میں اگر کوئی رکاوٹ یا مشکل پیش آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اس مقصد کے لیے تین اہم حقیقتیں ذہن میں رکھنی چاہئیں: اول، اسلامی نظام کے قیام کے لیے قیادت کی تبدیلی ضروری ہے؛ دوم، ملک میں آئینی و جمہوری نظام رائج ہے اور قیادت کی تبدیلی کا واحد راستہ انتخابات ہیں؛ اور سوم، غیر آئینی طریقہ شرعاً جائز نہیں، اس لیے جماعت کو صرف آئینی و جمہوری طریقوں سے اصلاح و انقلاب کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ان اصولوں کی روشنی میں جماعت کے لیے اسلامی نظام کے قیام کا واحد راستہ انتخابات کے ذریعے جمہوری جدوجہد ہی ہے۔
بعض اسلامی تحریکوں نے وقت کے ساتھ اپنی تنظیمی ساخت اور حکمتِ عملی میں بھی تبدیلیاں کیں تاکہ وہ بدلتے ہوئے حالات میں باقی رہ سکیں اور اپنا سماجی و فکری اثر برقرار رکھ سکیں۔ عرب بہار کے بعد، تیونس کی النہضہ تحریک نے جمہوری عمل میں حصہ لینے کے لیے اپنی حکمتِ عملی اور اسٹرکچر میں نمایاں تبدیلی کی، جس کا مقصد ایک جمہوری اور جامع معاشرہ inclusive society) ) قائم کرنا ہے۔ اس کے برعکس، مصر کی اخوان المسلمون کو شدید ریاستی جبر اور اندرونی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں تنظیم کے اندر دو رجحانات ابھرے — کچھ نے پرامن جمہوری جدوجہد کا راستہ اختیار کیا اور کچھ نے مزاحمت کو ترجیح دی۔ اسلامی تحریکوں نے وقت کے ساتھ سیکولرزم، جمہوریت، قوم پرستی اور غیر اسلامی حکومتوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں حقیقت پسندانہ، تدریجی اور پرامن حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے کئی اسباب کارفرما ہیں: عالمی سیاسی حالات، بین الاقوامی رجحانات، دعوت و اصلاح کے نئے مواقع اور معاشرتی حالات و ضروریات۔ موجودہ تناظر میں جو مسائل سامنے آرہے ہیں ان میں شہری حقوق، مذہبی آزادی، جمہوری عمل میں شرکت اور تدریجی اصلاح جیسے معاملات کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں اس امر کی غماز ہیں کہ اسلامی تحریکیں جامد نہیں بلکہ متحرک اور فکری اجتہاد پر گامزن ہیں۔ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنی حکمت عملی اور اندازِ کار میں مناسب تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
وقت گزرنے کے ساتھ جماعت اسلامی ہند نے بھی یہ ادراک کیا کہ مکمل علیحدگی اور سیاسی مقاطعہ کے ذریعے مطلوبہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس فہم کی بنیاد پر جماعت نے جمہوری اور دستوری دائرے میں رہتے ہوئے اصلاح کی راہ اپنائی ہے۔ اس تبدیلی میں اسلامی اصولوں کے مطابق اجتماعی مشاورت اور تدریجی ارتقا کو مرکزی حیثیت دی گئی۔
مذہبی اور سیکولر جمہوری نظام مملکت – موازنہ
واضح اسلامی فریم ورک کے باوجود یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ خلافت راشدہ کے شورائی نظام کے بعد کی مسلم سیاسی تاریخ نرم گرم بادشاہت یا بادشاہت کے تابع امارت، نوابی اور جاگیرداری جیسے غیرجمہوری، غیرشورائی اورغیرشرعی طرز حکم رانی کی عکاس ہے۔ اس انحراف کے نظریاتی، سماجی اور سیاسی اسباب پر اہل علم نے بحث کی ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں بادشاہت یا آمریت کے تسلسل کی بنیادی وجہ ابتدائی دور میں ہی خلافت راشدہ سے ملوکیت کی طرف منتقلی ہے۔ خلافت راشدہ نہ صرف ایک سیاسی حکومت تھی بلکہ نبوت کی مکمل نیابت پر مبنی تھی، جہاں خلیفہ پورے اسلامی نظام کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلانے کا ذمہ دار تھا اور اس کا انتخاب شورائی اور اس وقت کے تمدنی حالات میں عوامی قبولیت پر استوار تھا۔ لیکن کچھ وقتی حالات اور قبائلی اثرات کی وجہ سے اس نظام خلافت کو طویل مدت تک تسلسل کا موقع نہ مل سکا جو عوام الناس کو شورائی اور انتخابی قدروں کا خوگر بنا دیتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سیاسی عروج نے خلافت کے آئینی تصور کو ختم کر کے ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ یہ ملوکیت ایسی خود مختارانہ حکومت تھی جس میں حکم رانی کا سلسلہ خاندان کے اندر محدود ہو گیا اور اقتدار کے لیے سیاسی سازشیں عام ہو گئیں۔ بعد کے ادوار میں اس نئے نظام کے تحت بادشاہ یا امیر خود کو خدا کا نمائندہ قرار دینے لگے تاکہ اپنی حکم رانی کو مذہب کے نام پر مستحکم کر سکیں۔ اس کے علاوہ، سماجی سطح پر قبائلی اور فرقہ وارانہ تقسیم نے حکمراں طبقات کو اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مدد دی، جب کہ تعلیمی و فکری پسماندگی اور وسائل کی ناہموار تقسیم نے عوام کو سیاسی شرکت سے دور رکھا، جس سے آمریت کو دوام ملا۔ سیاسی طور پر جمہوری اداروں کی کم زوری اور قانون کی بالادستی کے اصول کی پامالی نے حکم رانوں کو بلا روک ٹوک اقتدار برقرار رکھنے کا موقع دیا۔ بیرونی طاقتوں نے بھی مسلم ممالک میں بادشاہوں اور آمروں کی پشت پناہی کی تاکہ اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کو تحفظ فراہم کریں۔ اس طرح اقتدار کا ارتکاز اور جانشینی کے غیر جمہوری اصولوں نے مسلم معاشروں میں آمریت اور بادشاہت کی روایات کو قائم و دائم رکھا۔
دوسری طرف اسی طرح کے بادشاہی، قبائلی اور جاگیردارانہ نظام پر مشتمل یوروپی مملکتیں نشاہ ثانیہ کے بعد اٹھنے والی تحریکوں، پاپائیت کی بالادستی کے خاتمے اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں بتدریج جمہوریت کی طرف گامزن ہوتی چلی گئیں۔ تعلیمی و معاشی ترقی اور سماجی و سیاسی انقلاب کے نتیجے میں مغربی معاشرے جمہوری قدروں کے خوگر ہوتے چلے گئے۔ دستوری نظام مملکت کی نشوونما اور بنیادی حقوق کے بندوبست نے جمہوری ادارہ سازی کی راہ ہم وار کی۔ تمدنی ترقی نے انتخابی عمل میں عوامی شرکت کو مسلسل آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح مغربی دنیا میں جمہوریت کو مستحکم ہونے کی سازگار فضا میسر ہوتی چلی گئی اور سیکولر جمہوری نظام کو ایک آئیڈیل نظام مملکت کا مقام حاصل ہوگیا جو اپنی بہت ساری خامیوں کو سیاسی تجربات کی روشنی میں دور کرنے کے عمل سے گزرتا رہا ہے۔
مذہب کی بنیاد پر بننے والے نظام مملکت میں پائی جانے والی کم زوریوں کی نشان دہی کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ مذہبی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی، اہم عہدوں سے محرومی، غیرجانب دارانہ احتساب کے فقدان اور شہری مساوات کے خاتمے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم یہ کم زوریاں صرف مذہبی ریاستوں تک محدود نہیں بلکہ سیکولر جمہوریتیں بھی جب اکثریت پسندی (majoritarianism)یا عصبیت کا شکار ہوجائیں تو وہاں بھی یہی مسائل سامنے آسکتے ہیں، جیسا کہ آج کل بعض بڑی جمہوریتوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔
درحقیقت نظام مملکت مذہبی ہو یا سیکولر، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بااصول اور باکردار افراد منتخب ہو کر نہ آئیں اور انتظامیہ و عدلیہ میں دیانتدار لوگ موجود نہ ہوں، کوئی بھی نظام عدل و مساوات کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یعنی نظام کی کام یابی کا دارومدار اس کو چلانے والے افراد کی صلاحیت اور کردار پر بھی ہے، نہ کہ صرف نظریاتی بنیادوں پر۔ دونوں نظاموں میں اکثریتی گروہ کی بالادستی اور جانب دارانہ رویے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ مذہبی ریاست میں مذہبی اکثریت اور سیکولر جمہوریت میں نسلی، لسانی یا کوئی اور اکثریت اقلیتوں کے حقوق کو پامال کر سکتی ہے۔ اس لیے نظام میں طاقت کے توازن اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مؤثر انتظامات بھی لازم ہیں اور حکومتی اداروں میں اچھے افراد کی موجودگی بھی ضروری ہے۔
لیکن اگر یہ مان کر گفتگو کی جائے کہ دونوں ہی طرز حکومت میں منتخب نمائندے اور سرکاری اہلکار دستور و قانون کے پابند ہوں تو کس نظام مملکت میں عدل و انصاف اور کم زور طبقات کے حقوق کا تحفظ زیادہ یقینی ہے۔ اس نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو آئینی و ادارہ جاتی تحفظات کے حوالے سے، اسلامی نظام مملکت میں اصولی طور پر خدا کی ہدایت کو بالا دست حیثیت حاصل ہے اور عوام کو حق حاصل ہے کہ کسی بھی غیر عادلانہ قانون سازی کو چیلنج کرکے اسے غیر شرعی قرار دلواسکتے ہیں۔ ایسی صورت میں پارلیمانی اکثریت بھی حکم الہی کے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور ہوگی۔ دوسرے یہ کہ قرآن و سنت میں دیے گئے انسانی حقوق کو کسی بھی بہانے نہ تو سلب کیا جا سکتا ہے اور نہ معطل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس پر تحدید لگائی جاسکتی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی قانون سازی باطل ہے۔ لیکن یہ اصولی پوزیشن سیکولر نظام مملکت کی نہیں ہے۔ سیکولر جمہوریت میں قانون سازی کا غیر محدود اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہوتا ہے اور اگر وہ اکثریتی دباؤ میں آ کر جانب دارانہ قانون سازی کرنا چاہیں تو عدلیہ بھی اکثر صورت حال میں مداخلت نہیں کر سکتی، خصوصاً جب قانون سازی آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہ ہو۔ اس لحاظ سے، اسلامی ریاست میں قانون سازی کی ایک واضح حد موجود ہے جو خدا کی ہدایت ہے، جب کہ سیکولر نظام میں قانون سازی کی حدود نسبتاً وسیع ہیں بشرطیکہ اس میں عوامی نمائندوں کی مرضی پر کوئی بالادست قانون قدغن لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ چناں چہ سیکولر جمہوریت میں اکثریت کو زیادہ من مانی کے دستوری مواقع حاصل ہیں جو اصولی، قانونی اور دستوری طور پر کم زور طبقات کو ریاست کے سامنے زیادہ غیر محفوظ (vulnerable)بنانے والے ہیں۔
بہر حال اسلامی تحریکوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ان ممالک میں جہاں کی اکثریت حاکمیت الہ اور شورائیت کی قائل ہے، وہاں اسلامی فریم ورک میں ایک شمولی (،(inclusiveشورائی اور عادلانہ نظام مملکت کا کام یاب نمونہ پیش کریں جو جدید جمہوری نظام کی خوبیوں سے آراستہ اور خامیوں سے پاک ہو۔ یہ ایک نظریاتی ہدف، علمی چیلنج اور عملی پروگرام ہے جسے پورا کرنے کے لیے تحریک اسلامی کو عوام سے خواص تک معاشرے کے بڑے طبقے کو قائل اور تیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔