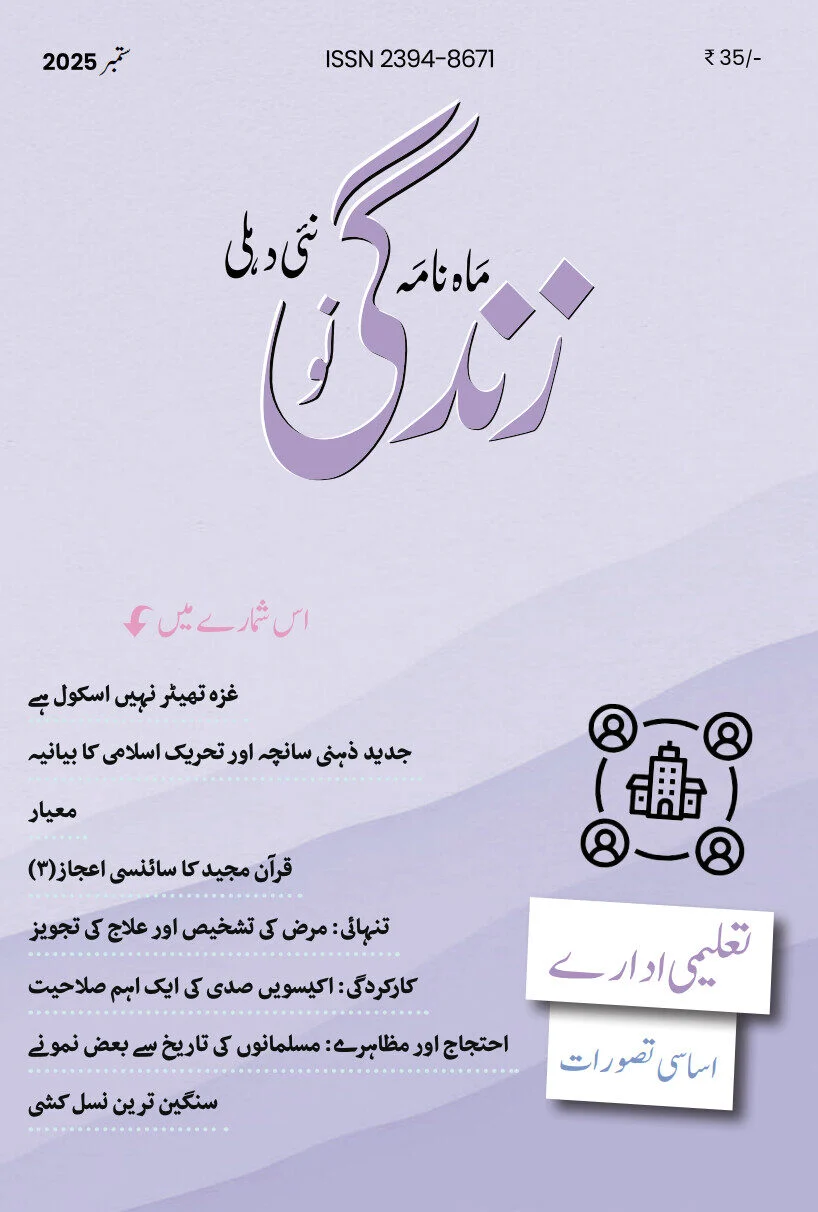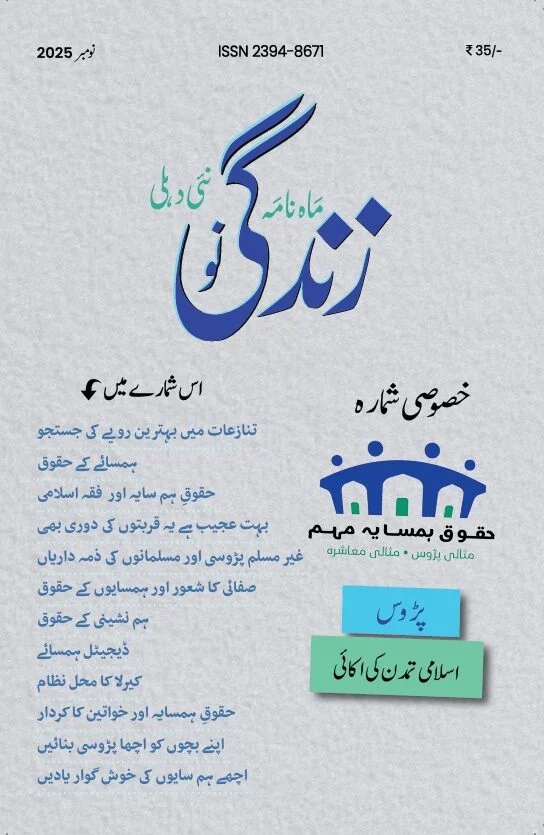398ھ/1009ء کے دوران مصر میں اناج اس قدر مہنگا ہوگیا کہ لوگ روٹی کے لیے کتوں کی طرح لڑنے لگے۔ آخرکار لوگوں نے گندم کی قلت اور خراب گندم کی فراہمی کو لے کر احتجاج کیا اور طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہاتھوں میں روٹی کے ٹکڑے لیے مصر کے فاطمی فرماں روا حاکم بامر اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔
مسلمانوں کی طویل تاریخ کا یہ شاید پہلا انوکھا اور پرامن شہری احتجاج تھا۔ اسلامی تاریخ اس قسم کے احتجاج کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔
غور کرنےسے معلوم ہوتا ہے اس پر امن جدوجہد کے پیچھے جو شرعی جواز ودلائل کار فرما تھے وہ مظلوم کو اپنی مظلومیت کے اظہار اور حق داروں کو اپنے حقوق کی خاطر مزاحمت کی تحریک و ہمت عطا کرنے والے تھے۔ مظلوموں اور مستحقین کے اندر یہ تحریک پیدا کرنے والی اولین ذات نبی کریمﷺ کی ہے۔آپؐ حاجت مندوں کی باتوں کو غور سے سنا کرتے اور ان رکاوٹوں کو دور فرمایا کرتے جو حق داروں اور مظلوموں کو اپنی بات کھل کر رکھنے سے روکتی ہوں، بلکہ آپؐ نے تو حکم رانوں کے لیے اس بات کو حرام قرار دیا کہ وہ عوام ورعایا سے حجاب میں رہیں:
من ولِی من أمر الناس شیئا فاحتجب عن أولی الضعفة والحاجة احتجب الله عنه یوم القیامة (رواه أحمد والطبرانی)
’’جس شخص کو لوگوں کے معاملات کی ذمے داری سونپی گئی ہو اور وہ کم زوروں اور حاجت مندوں سے حجاب رکھے تو اللہ قیامت کے دن اس سےحجاب کر لے گا۔ ‘‘
نبیﷺ کے بعد خلفائے راشدین آئے جنھوں نے امت کے دلوں اور ان کی عملی زندگی میں اقتدار کے خلاف ’’احتجاج کا فہم وشعور‘‘ پیوست کیا اور آگاہ کیا کہ اہل اقتدار کی جن پالیسیوں کو آپ مسترد کرتے ہیں ان پر اعتراض کرنا آپ کا حق ہے۔ پھرسرکردہ مصلح علما (محدثین، فقہا، صوفیا و صلحائے کرام) کا دور آیا۔ یہ حضرات اپنے حقیقی کردار سے آگاہ تھے۔ یعنی یہ کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے مسائل و معاملات کو محسوس کیا جائے۔ اسی چیز نے انھیں امت کی عمومی قیادت و رہ نمائی کے لائق بنایا۔ امت کے معاملات میں علمائے کرام کی مثبت شمولیت نے اسلامی معاشرے کو زندگی بخشی۔ اس طرح مظالم کے خلاف مزاحمت اور ظلم و جور کو ختم کرنے کے سلسلے میں مسلم رائے عامہ مزیدموثر ہوئی۔
عملی سطح پر مسلمانوں نے شہری احتجاج کے لیے مختلف اندازاور طریقے اختیار کیے، مثلاً عوام الناس کو جمع کیا، مظاہرے کیے، ہڑتالیں کیں، بائیکاٹ کیا، عام نظام کو معطل کیا، مطالبات پر مشتمل عرض داشتیں لکھ کر حکومت کے سامنے پیش کیں اور جس طرح اہل مصر نے ہاتھو ں میں روٹی کے ٹکڑے لے کر غلے کی گرانی کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، اسی طرح مختلف احتجاجی علامتوں کااستعمال کیا۔
شدید اور پریشان کن حالات کے دوران مساجد میں دعاؤں کا اہتمام بھی مسلمانوں کا ایک معروف اور موثر احتجاجی طریقہ رہا ہے۔ ان احتجاجی سرگرمیوں کے دوران اس وقت تصادم اور مزاحمت کی کیفیت بھی دیکھنے کو ملتی تھی جب اختلاف رائے یا حقوق کا مطالبہ کرنے کی بنیاد پر قید کیے جانے والے لوگوں کی رہائی کے لیے جیلوں پر ہلہ بول دیا جاتا۔
احتجاج کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ حکومتی پالیسی یا فیصلےکی وجہ سے جب اسباب زندگی متاثر ہوجاتے تو اس صورت میں مختلف مذہبی طبقات کے درمیان اتحاد کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی۔ ظلم وعدوان کے خلاف انجام پانے والے عوامی مظاہروں میں الگ الگ مذہبی علامات کو نمایاں کرکے تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ میں پیشہ ور اور کاروباری طبقوں کے احتجاج اور مزدوروں کی ہڑتال کا بھی ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے بازاروں پر تالے لگ جایا کرتے تھے۔
احتجاج کے بعض طریقے تو اس انتہا کو پہنچ جاتےکہ مسجدوںمیں باجماعت نمازوں کا سلسلہ معطل ہو کر رہ جاتا۔ ایسا اس وقت ہوتا جب حکومتیں امن و امان کی فراہمی میں کوتاہ ثابت ہوتیں۔ گورنروں، حکومتی کارندوں، ججوں اور وزرا کو عوام کے ہاتھوں معطل بھی ہونا پڑتا، یا پر امن احتجاج ایک بھیانک بغاوت کی صورت اختیار کر لیتا اور حکومت اور اس کے ارکان کا تختہ پلٹ دیتا۔
ابتدائی دور کی چند تصویریں
خلفائے راشدین کا دور آیا تو انھوں نے امت کے دلوں میں احتجاج کا’فہم‘ راسخ اور پختہ کیا۔انھوں نے امت کو واقف کرایاکہ انھیں حکومت کی کوئی پالیسی قابل اعتراض نظر آئے تو اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کرانا ان کا حق ہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین اپنے عہد کے آغاز میں عوامی خطاب کے دوران یہ اعلان فرمایا کرتے کہ وہ عوامی جواب دہی سے ماورا نہیں اور ان کی پالیسیاں تنقیدو اصلاح سے بالاتر نہیں ہیں۔
حضرت امام مالک بن انسؓ (م: 179ھ/ 795ء)نے موطا میں یہ روایت نقل کی ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ (م: 13ھ/ 635ء)نے بیعت مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام سے خطاب فرمایا تو یہ بھی فرمایا: ’’اما بعد، مجھے آپ لوگوں کے معاملات کا ذمے دار بنا دیا گیا ہے حالاں کہ میں آپ لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔۔۔، لوگو، میں اللہ کی پیروی کروں گا، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کروں گا۔ جب میں اپنی ذمے داری کو احسن طریقے سے انجام دوں تو میری مدد کرنا، اور اگر کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔‘‘
اس خطاب کا مطلب یہ ہے کہ امت کو اپنے معاملات میں مکمل اختیار حاصل ہے۔ وہ جسے چاہے خلیفہ منتخب کرے، جسے چاہے معزول کر ے، اس سے اختلاف کرے، اس کے خلاف احتجاج کرے، اس کی نگرانی کرے اور ضرورت پڑنے پر اسے سیدھا کر دے۔ اسی لیے امام مالکؒ نے حضرت صدیقؓ کے اس قول پر یہ تبصرہ کیا ہے: ’’کوئی شخص اگر حکم راں بن سکتا ہے تو صرف اسی شرط پر بن سکتا ہے۔‘‘
امام ذہبی (م: 748ھ /1347ء) تاریخ الاسلام میں ذکر کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ (م: 23ھ / 645ء) کی ملاقات ایک روز جلیل القدر صحابی محمد بن مسلمہ (م: 46ھ / 667ء) سے ہوئی تو ان سے فرمایا:’’مجھے کیسا دیکھتے ہو؟‘‘ کہا: ’’جیسا میں چاہتا ہوں۔۔۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ مال جمع کرنے پر قادر ہیں، لیکن اس سے بے نیاز و کنارہ کش رہتے ہیں، اس کی تقسیم میں عادل ومنصف ہیں۔ اگر آپ [مال کی طرف] مائل ہوئے تو ہم آپ کو اسی طرح سیدھا کر دیں گے جس طرح نیزے کو سیدھا کیاجاتا ہے۔‘‘
ایسا نہیں تھا کہ یہ اصول خلفائے راشدین اور رعایا کے درمیان ذاتی و شخصی نوعیت کے معاملات کے ساتھ مخصوص رہے ہوں، بلکہ ان اصولوں کو مستقل دستور کی حیثیت حاصل تھی، جس پر اکثر اوقات خلافت راشدہ کے حکام اور ریاستی گورنر عامل رہا کرتےتھے۔ بلکہ خلفا اپنے عام ملازمین کو ان اصولوں کا پابند کیا کرتے تھے۔ امام بیہقیؒ (م: 458ھ/ 1067ء) نے ’السنن الکبریٰ‘ میں روایت نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت عمرؓ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا:
’’سنو، میں اپنے کارندے تمھارے پاس اس لیے روانہ کرتا ہوں تاکہ وہ تمھیں دین کی تعلیم اور سنت کا علم دیں۔ اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمھارا ناطقہ بند کریں اور تمھارے مال پر دست درازی کریں۔ سنو، اگر کسی کو اس طرح کا کوئی شک محسوس ہو تو وہ اس کی شکایت مجھ تک پہنچائے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں اس سے اس کا پورا بدلہ لوں گا۔‘‘ اس کے بعد آپؓ نے اپنے گورنروں کو مخاطب کرتے ہوئے تبنیہ کی: ’’سنو، مسلمانوں کو مارنا مت کہ وہ تمھاری تذلیل کرنے لگیں اور نہ ان کا حق روکنا کہ وہ تمھاری بے قدری کرنے لگیں۔‘‘
مسلمانوں کی طرف سے پر امن احتجاج کا پہلا عملی مظاہرہ حضرت عثمان بن عفانؓ (م: 35ھ / 656ء) کے زمانے میں ہوا، جب مختلف ریاستوں سے جمع ہونے والے ایک گروہ نے ان کی بعض پالیسیوں اور گورنروں کے خلاف احتجاج کیا تھا۔
اس سے قطعِ نظر کہ احتجاج کرنے والوں کے دعووں میں کتنی صداقت تھی، اور اس حقیقت کے باوجود کہ اس احتجاج میں سختی اور تشدد کا استعمال کیا گیا تھا، خلیفہ حضرت عثمانؓ نے ان کے احتجاج کو تسلیم کیا اور اس طرح کام یابی کے ساتھ امت کے اس حق کی ضمانت فراہم کی کہ وہ اپنے ذمے داروں کے خلاف اپنی آواز رکھ سکیں۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ حضرت عثمانؓ نے احتجاج کو منتشر کرنے کی کوشش اور صحابہ کرام کی مداخلت کو بھی مسترد کر دیا تھا جو کہ خود ان کی زندگی کو بچانے کے لیے مظاہرین سے جنگ کرنے پر آمادہ تھے۔
اس تعلق سے امام ابن کثیرؒ (م: 774ھ/1372ء) کہتے ہیں: ’’حضرت عثمانؓ کے گھر کے اندر اُس وقت مہاجرین و انصار کے تقریباً ستّر فرزندگان موجود تھے۔ اگر حضرت عثمانؓ نے انھیں اجازت دی ہوتی تو وہ آپؓ کا دفاع کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت عثمانؓ نے اپنے قریب موجود ان لوگوں سے کہا: ’’جس پرمیرا کچھ بھی حق ہے، میں اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اپنا ہاتھ روکے رہے اور اپنے گھر کی طرف چلا جائے۔ پھر اپنے غلاموں سے فرمایا: ’’جو اپنی تلوار میان میں رکھ لے وہ آزاد ہے۔‘‘
طویل راستہ
خلیفہ سوم حضرت عثمانؒ کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ، جس کا آغاز تو پرامن انداز میں ہوا تھا، لیکن اختتام ان کی شہادت پر ہوا، ان سیاسی و سماجی مظاہروں کے ایک طویل سلسلے کی بنیاد بنا، جس کی تفصیلات کو انتہائی باریکی کے ساتھ تاریخ اسلامی کے ہر دور میں مرتب اور محفوظ کیا گیا ہے۔
حضرت علی بن ابی طالبؓ (م: 40ھ/ 661ء) کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کے خاتمے سے پہلے ہی ان اصولوں کی تاسیس ہو چکی تھی جن میں مسلمانوں کا یہ حق تسلیم کیا گیاتھا کہ وہ اپنے حکم رانوں کی پالیسیوں پر احتجاج اور تنقیدکا حق رکھتے ہیں۔ حکم راں دراصل امت کے عمومی وخصوصی مفادات و مصالح کے حصول کے سلسلے میں امت کے ہی نائب ونمائندہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر احتجاج مبنی بر حقیقت اسباب کی بنا پربرپا ہوا ہو، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک شکل قرار پاتا ہے کیوں کہ ’’سلطان کا احتساب ضروری ہے۔‘‘
یہ وہ نظریاتی و عملی ورثہ ہے جو خلفائے راشدین کی پالیسیوں پر نظر رکھنے کے سلسلے میں صحابہ و تابعین کو پابند بناتا تھا، اسی ورثے کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اکثر حالات میں تمام تر احتجاجی مواقع پر اموی اقتدار کا سامنا کیا۔ اس احتجاجی مزاحمت کا آغاز اموی خلافت کے بانی حضرت معاویہ بن ابی سفیان (م: 60ھ/681ء) سے ہوا اور آخری اموی خلیفہ کے زندہ رہنے تک جاری رہا۔
حضرت معاویہؓ کی جانب سے اپنے فرزند یزید(64ھ/ 685ء) کو اقتدار کا وارث بنانےکا فیصلہ امویوں کے خلاف احتجاجی سلسلے کی اولین کڑی ثابت ہوا۔ امیر معاویہؓ نے حجاز کے گورنر مروان بن الحکم (م:65ھ/686ء) کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے اندر ان کے بیٹے یزید کی ولی عہدی پر صحابہ کرام کی بیعت حاصل کریں۔ صحابۂ کرام کی ایک جماعت نے اعتراض درج کراتے ہوئے اس فیصلےکو چیلنج کر دیا جس کے خطرناک اثرات آئندہ مسلمانوں کی تاریخ پر پڑنے والے تھے۔
امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: ’’مروان حجاز کا حاکم تھا، حضرت معاویہ نے اسے وہاں کا گورنر بنایا تھا۔ اس نے خطاب کیا اور خطاب کے دوران اس نیت سے یزید کا نام لیا کہ والد کے بعد اس کے حق میں بیعت کی جائے۔ اس سلسلے میں مروان نے کہا: یہ ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) کی سنت ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے جواب دیا: ’’یہ[ابوبکر و عمر کی نہیں] ہرقل اور قیصر کی سنت ہے۔‘‘(الاصابہ فی تمییز الصحابہ)
مروان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ معاویہؓ نےجانشین کے طور پر اپنے بیٹے کا نام حضرت ابوبکرؓ کی تقلید میں پیش کیا ہے کہ انھوں نے بھی اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمرؓ کا نام تجویز کیا تھا۔ لیکن اس معاملےمیں صحابہؐ کرامؓ کا خیال یہ تھا کہ یہاں قیصرانِ روم کی تقلید کی گئی ہے جو اپنے بعد اپنے بیٹوں کو بادشاہت منتقل کردیتے ہیں۔ اس کی وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام سیوطی (م:911ھ/1506ء) نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے: ’’حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کھڑے ہوئے اور کہا: ’’بلکہ یہ تو کسریٰ اور قیصر کی سنت ہے۔ ابوبکر اور عمر (رضی اللہ عنہما) دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی اولاد یا اپنے گھر کے کسی فرد کو اپنا وارث نہیں بنایا تھا۔‘‘
حضرت عبدالرحمن کے اس جواب میں اس جانب بلیغ اشارہ بھی تھا کہ اموی گھرانے پرملکِ شام کا اثرہے جو پہلے رومیوں کے زیرحکومت رہ چکا ہے۔ اور خاص طور سے حضرت معاویہؓ پر اس ماحول کا اثر ہے جو (گورنر اور بعد میں خلیفہ کی حیثیت سے) تقریباً تیس سال سے شام کے حاکم چلے آ رہے تھے۔
ابن حجرایک ایسے واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے ساتھ اسی قسم کی احتجاجی صورت حال اس وقت پیش آئی جب وہ 51ھ/672ء میں حج کے ارادے سے حجاز آئے۔ اس وقت انھوں نے اہل مدینہ سے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینی چاہی۔’’ انھوں نے اہل مدینہ سے خطاب کیا اور لوگوں سے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر حضرات حسین بن علیؓ (م: 61ھ/682ء)، عبداللہ ابن الزبیر(م: 73ھ/690ء) اور عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم نے ان سے گفتگو کی۔ حضرت عبدالرحمن نے کہا: ’’کیا آپ ’ہرقل کے طریقے‘ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں؟! ایک قیصر مرتاہے اس کی جگہ دوسرا قیصر لے لیا کرتا ہے؟!خدا کی قسم ہم ہر گز ایسا نہیں کریں گے۔‘‘
امام سیوطی جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمرؓ (م: 73ھ/ 690ء) کی جانب سےپیش کردہ موثر و مضبوط اپیلوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اپیلیں ان اہل مدینہ کے دفاع میں کی گئی تھیں جو خلافت کو خاندانی وراثت میں تبدیل کیے جانے کے مخالف تھے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضرت معاویہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ’’اما بعد، آپ سے پہلے ایسے خلیفہ گزرے ہیں جن کے فرزندگان آپ کے بیٹوں سے کہیں زیادہ لائق تھے، لیکن انھیں اپنے فرزندوں میں بھی وہ صلاحیت نظر نہیں آئی جو آپ نے اپنے بیٹے میں دیکھ لی ہے۔ انھوں نے تو مسلمانوں کے لیے وہ شخص منتخب کیا جو ان کے علم میں سب سے افضل وبہتر تھا۔‘‘
حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے خلیفہ معاویہؓ کی دلیلوں کو سننے سے انکار کر دیا تو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓنے حضرت ابن عمرؓ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا: ’’ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں تو خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے۔ قسم ہے خدا کی، آپ یا تو اس معاملے کو مسلمانوں کی مجلس شوریٰ میں پیش کریں گے ورنہ ہم شدت کے ساتھ اسے آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔’’عبارت‘‘ شدت کے ساتھ واپس آپ کی طرف لوٹا دیں گے‘‘ میں اس بات کی واضح تنبیہ ہے کہ وہ اس معاملے کو پر امن احتجاج سے لے کر مسلح تحریک نافرمانی تک لے جانے کے لیے تیار ہیں۔‘‘
تاریخ اسلامی : رائے عامہ کی تاثیر
واقعات کا سلسلہ اسی رو میں چلتا رہا جدھر حضرت امیر معاویؓہ لے جانا چاہتے تھے اور آخرکار جب ان کا انتقال ہوا تو حکومت اور اقتدار ان کے بیٹے یزید کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر اقتدار کی یہی منتقلی امت کے اندر شدید غیظ وغضب کا سبب بنی جس کا سامنا یزید کو اپنے عہد میں کرنا پڑا۔ اس کے بعد مسلح انقلابی تحریکیں پھوٹ پڑیں جن کا سلسلہ اس کی موت کی بعد بھی نہیں تھما۔ مسلح انقلابی تحریکوں کے اس سلسلے کا آغاز حضرت زبیرؓ اور ان کے ساتھیوں کی تحریک سے ہوا، درمیان میں شیعہ، خوارج اور پھر حضرت عبدالرحمن بن اشعث کی فوجی قیادت میں فقہا کی انقلابی تحریک سے گزرتا ہوا امام زید بن علی الہاشمی (م: 126ھ/745ء) کی انقلابی تحریک پر ختم ہوا۔
بعد میں بعض اسباب سے اقتدار کی کنجیاں مروانی خاندان کے ہاتھوں میں آ گئیں اور خاص طور سے مروانی حکومت کا حقیقی بانی وموسس عبدالملک بن مروان (م: 86ھ/ 706ء) انقلابی جماعتوں پر غالب آنے میں اس لیے کام یاب ہو گیا کہ ان جماعتوں کےاصول و اہداف الگ الگ تھے۔ اس کے بعد یہ خاندان حکومت کرتا رہا اور تقریباً چار دہائیوں تک اس نے ایک بودا اورکم زور سا امن قائم کیے رکھا۔
132ھ/751ء میں امویوں کے اقتدار کا زوال ہو گیا۔ اس زوال کی وجہ ایک زبردست بغاوت تھی جس کی باگ ڈور عباسیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ عباسیوں کی آمد سےسیاسی پالیسیوں کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ان پالیسیوں کے متعلق عوام کی طرف سے اعتراضات کا اظہار بھی کیا گیا اور ان کے خلاف احتجاج اور مظاہرے بھی کیے گئے۔ احتجاج اور مظاہروں کا یہ سلسلہ عباسی خلافت کے مختلف ادوار میں جاری رہا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ سیاسی احتجاج اورمظاہرے کسی بھی زمانے یا کسی بھی دور اقتدار میں ہوئے ہوں، ان کے متعدد اسباب و محرکات ہوا کرتے تھے۔ احتجاجوں کی شکل و صورت اور اسالیب و انداز مختلف ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح ان مظاہروں کا سامنا کرنے والے خلفاء، مسلم سلاطین اور امراء کی جانب سے ردعمل بھی مختلف، یعنی کہیں مثبت تو کہیں منفی سامنے آیا کرتا تھا۔
مسلم تاریخ میں احتجاج کے بیش تر واقعات کا تعلق خالص اقتصادی اسباب و محرکات، مثلاً مہنگائی، سامان رسد کی قلت، فقر و فاقہ، بھاری بھرکم ٹیکس، اموال کی ظالمانہ ضبطی یا عوامی خزانے کے بے دریغ غلط استعمال سے رہا ہے۔
غذائی بحران، قیمتوں میں گرانی اور خراب معاشی صورت حال کی وجہ سے ہونے والے عوامی احتجاج کی ایک مثال امام ابن جوزی (م: 597ھ/ 1201ء) نے نقل کی ہے کہ بغداد میں 373ھ کے دوران زبردست مہنگائی آگئی تھی، کیوں کہ ’’ایک سال کے اندر ہی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی تھیں اور عوام پر خوف ناک قسم کی بھکمری طاری ہو گئی تھی۔۔۔، لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا، مسجدوں کے منبروں کو توڑ ڈالا، متعدد جامع مسجدوں میں نماز روک دی گئی، کم زور و ناتواں خلقت بھوک کے مارے راستوں پر دم توڑنے لگی۔ پھر سال کے اختتام پر قیمتیں کم ہوئیں۔‘‘ (المنتظم)
امام ابن حجر839ھ/1435ء کے دوران مصر کا حال بیان کرتے ہیں کہ ’’گندم کی قیمتیں مہنگی ہو گئیں اور یہ مہنگائی بڑھتی چلی گئی۔ دکانوں پر روٹیوں کی قلت ہو گئی تو عوام نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ چناں چہ سلطان نے غلّے کے سرکاری گوداموں کو کھولنے کا حکم دیا کہ وہاں سےغلہ بیچا جائے۔ اس سے حالات میں کچھ بہتری آئی اور حالات پرسکون ہوئے۔‘‘
ایک اور عوامی احتجاج، جس کا محرک معاش ہی تھا، کے متعلق ابن حجر کہتے ہیں کہ 775ھ/1373ء میں چیخ پکار کرتے ہوئے عوام میں سے ایک شخص قلعے (سلطان کی قیام گاہ) سے چپک کر چلانے لگا: ’’اپنے سلطان کو قتل کر دو، قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ ‘‘اس شخص کو گرفتار کرلیا گیا۔ اسے کوڑوں سے مارا گیا اور شہر میں اس کی تشہیر کی گئی۔ ‘‘
یہ واقعہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اقتدار کو یہ خطرہ لاحق رہتاتھا کہ اس قسم کی الگ الگ اقتدار مخالف تحریکیں بڑھتی نہ چلی جائیں۔اسی طرح یہ واقعہ رائے عامہ کی بے باکی کے علاوہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ مسلم عوام ٹھہرے ہوئے پانی میں ہلچل پیدا کر دیا کرتے تھے خواہ اس سے ان کی زندگی خطرات سے دوچار ہو اور ان کی روزی روٹی چلی جائے۔
سیاسی محرکات
ان احتجاجی سرگرمیوں کے پس پشت کارفرما سیاسی اسباب ووجوہ بھی اہمیت کے اعتبار سے اقتصادی و معاشی اسباب سے کم نہیں تھے۔ احتجاج کی ایک سیاسی وجہ کبھی کبھی یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ کسی مخصوص اہل کار کی سیرت و کردار میں لوگوں کو انتظامی، فکری یا اخلاقی فساد نظر آتا تو اسے عہدہ ومنصب سونپے جانے کے خلاف احتجاجی تحریک چلا دیتے۔
یعنی گورنروں کا تقرر یا معزولی کا مسئلہ محض اتنا نہیں تھا کہ سلطان کا حکم ہے، جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ ان کے سلسلے میں عوام کی رضامندی بھی اہم تھی۔ یہ وہی چیز ہے جسے موجودہ علم سیاسیات میں ’’عوامی خود مختاری‘‘ یا ’’عوامی مقبولیت‘‘ کہا جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین گورنر اور دوسرے اہل کاروں کی تعیین کے سلسلے میں عوام کی رضامندی کا خیال رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ’’اہل کوفہ نے حضرت عمرؓ سے حضرت سعد (بن ابی وقاصؓ) کی شکایت کی۔ چناں چہ انھوں نے حضرت سعؓدکو معزول کرکے حضرت عمار بن یاسرؓ کو گورنر مقرر کر دیا۔ امام ذہبیؒ کے مطابق یہ 22ھ/ 644ء کی بات ہے۔
اسی سے ملتا جلتا واقعہ کئی صدیوں بعد مصر میں پیش آیاتھا، جو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ حکومت پر دباؤ بنانے والے عوامی احتجاجات کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا اور جغرافیائی اعتبار سے اس میں وسعت آتی گئی۔ ابن حجر ’اِنباء الغُمَر‘ میں لکھتے ہیں:775ھ/ 1374ء میں ’’عوام قرآن ہاتھوں میں لے کر جمع ہوئے اور مطالبہ کیا کہ علاء الدین بن عرب (م: 781ھ/1379ء)کو محتسب کے عہدے سے معزول کیا جائے، چناں چہ اسے معزول کر دیا گیا۔‘‘وہ کہتے ہیں کہ 791ھ/1389ء میں عوام نے محتسب کی شکایت کی تو امیر نے اسے بلوایا اور دو سو کوڑے مارنے کے بعد اسے معزول کر دیا۔‘‘
عبد الرزاق الجرکسی (م: 868ھ/1463ء) کے حالات زندگی میں امام سخاوی اپنی کتاب ’’الضوء اللامع‘‘ میں کہتے ہیں کہ اسے شام کے حلب کا گورنر بنایا گیا۔ ’’وہاں اسے پسندنہیں کیا گیا اور اہل حلب نے اسے مسترد کردیا، چناں چہ وہ معزول کر دیا گیا۔۔۔۔ اس کے بعد اسے شام (دمشق) کی جانشینی عطا کی گئی، لیکن یہاں بھی لالچ، بخیلی، ہوس اور فضول خرچی جیسی برائیوں کی وجہ سے اس کے کردار کو سراہا نہیں گیا اور آخرکار انہی اوصاف کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوا۔۔۔، اس کی موت سے اہل دمشق کو بہت خوشی ہوئی۔ لوگوں نے اس کی تدفین نہیں ہونے دی، اس لیے موت کے دو دن بعد اسے دفن کیا جا سکا۔‘‘
یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ظالموں اور مفسدوں کی موت پر خوش ہوتے اور احتجاج کے طور پر اپنے قبرستانوں میں دفنانے سے روکنے کے لیے مظاہرہ کرتے۔ یہ سماجی دباؤ کی وہ شکل تھی جو عوامی امور و معاملات میں غلط راہ اختیار کرنے والےکوخوف زدہ کرتی تھی۔
مذہبی ایکتا
احتجاج کے سیاسی اسباب میں سے ایک امن کی صورت حال کو کنٹرول کرنے میں حکومت کی کوتاہی اور عوامی امن وسلامتی کی فراہمی میں ناکامی ہوا کرتا تھا۔ اس ناکامی پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنےکے لیے عوام سڑکوں پر نکل آتے۔ امام ذہبیؒ ہمیں کتاب ’العبر‘ میں 421ھ/1031ء کے دوران عراق کے امن وامان کی سیاہ تصویر دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تمام مذہبی طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مل جل کران پریشان کن حالات کا کیسے مقابلہ کیا۔
امام ذہبی کہتے ہیں: ’’رہی بات بغداد کی، توحکومت کا رعب ودبدبہ ختم ہو جانے اور مسلسل دھوکے اور فریب کی وجہ سے اس پر فساد و تباہی تقریباً غالب آ چکی تھی۔ چناں چہ ہاشمیوں نے جامع المنصور میں جمع ہو کر ہاتھوں میں قرآن اٹھائے اور لوگوں سے احتجاج کی اپیل کی۔ فقہائے کرام اور امامیہ شیعوں کی ایک تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی اور سب نے اس سخت آزمائش اور سنگین بحران پر احتجاج کیا۔ اسی طرح لوگ اس وقت بھی جمع ہوئے تھے جب بازنطینیوں نے شام کےعلاقوں اور شمالی عراق کے جزیرہ فراتیہ پر حملہ کر دیاتھا۔‘‘
بعض اوقات لوگوں کی طرف سے احتجاج اور مظاہرےکی وجہ دینی یا مذہبی بھی ہوا کرتی تھی۔ یعنی جب انھیں لگتا تھا کہ ان کے مذہبی عقائد و مقدسات پر ضرب لگ رہی ہے تو اس کے خلاف مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اس کی قدیم ترین مثال علامہ سیوطی نے ’تاریخ الخلفاء‘ میں ’حَرّة کی انقلابی تحریک‘ کے اسباب بیان کرتے ہوئے پیش کی ہے جس کا تعلق 63ھ/ 684ء سے ہے۔ یزید بن معاویہ کے عہد کی بات ہے کہ عام مسلمان مدینہ منورہ میں مہاجر و انصار صحابہ کی قیادت میں اموی حکومت کے خلاف جمع ہوئے تھے۔ سیوطی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ یزید گناہ و معصیت میں حد سے زیادہ گزر گیا تھا۔‘‘
خلیفہ ہشام بن عبدالملک (م: 125ھ/ 744ء) کے بعد اس کا وارث اور بھتیجا ولید بن یزید (م: 126ھ/ 745ء) مسند خلافت پر بیٹھا ہی تھا کہ امت نے اس لیے احتجاجی مظاہرے برپا کر دیے کہ اس نے محرّمات کی توہین کی تھی اور دین کا مذاق اڑایا تھا۔
امام ابن کثیر(م: 774ھ/ 1372ء) البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے احتجاج کے خوف کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اسے اس بے حرمتی و تمسخر سے باز رکھ سکتی ہو۔
اس نے ایک بار کعبے کی چھت پر خیمہ نصب کرنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اور اس کے احباب وہاں شراب اور موسیقی جیسی منکرات سے لطف اندوز ہوں۔ لیکن مکہ پہنچا تو اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی جسارت نہیں کر سکا، کیوں کہ اسے لوگو ں کی طرف سے انکار و مخالفت کا ڈر ہوا۔ البتہ وہ اپنے اسی انحرافی رویے پر اس وقت تک قائم رہا جب تک ایک فیصلہ کن بغاوت کے ذریعے اسے اقتدار سے برطرف نہیں کر دیا گیا۔
ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جن میں عوام ان لوگوں کے خلاف متحرک نظر آتے ہیں جو دینی تعلیمات اور عقیدے کے مسائل میں جمہور و اکثریت کے نزدیک ثابت شدہ موقف کے خلاف جاتے تھے۔ مثال کے طور پر حافظ ابن حجر نے’لسان المیزان‘میں قاضی شعْبَوَیہ بن سہل رازی (م: 246ھ/ 860ء) کے حالات زندگی نقل کیے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں: ’’عباسی خلفیہ معتصم نے انھیں عہدہ قضا اور جامع الرصافہ(بغداد) کی امامت پر مامور کیا۔۔۔۔۔ قاضی شعبویہ اہل سنت سے متنفر تھے اور ان کی تنقیص کیا کرتے تھے۔انھوں نے اپنی مسجد کے دروازے پر ’’قرآن مخلوق ہے‘‘ لکھ رکھا تھا۔ عوام نے مسجد کا دروازہ ہی جلا دیا۔‘‘
ظالموں کے دل کا چور
اسی لیے اقتدار، خواہ کتنا ہی طاقت ور رہا ہو، عوام کے لحاظ سے کام کرتا تھا اور ان کی تحریکوں سے خوف کھاتا تھا۔ امام طبری (310ھ/922ء) تاریخ طبری میں رقم طراز ہیں کہ 284ھ/ 997ء میں عباسی خلیفہ معتضد باللہ (م: 289ھ/ 902ء) نے فیصلہ کیا کہ منبروں سے معاویہ بن ابی سفیانؓ پر لعنت بھجوائے گا۔ اس سلسلے میں ایک فرمان تیار کرنے کا حکم بھی دیا جو لوگوں کو پڑھ کر سنایا جا سکے۔‘‘
معتضد اپنے اس فیصلے سے اس وقت تک باز نہیں آیا جب تک اس کے سرکاری مشیرانِ خاص نے اسے اس بات کا خوف نہیں دلایا کہ’’عوام کے اندر بے چینی پھیل جائے گی اور اس فرمان کو سنتے ہی وہ احتجاجی تحریک شروع کر دیں گے‘‘اور اس کے نتیجے میں جو عوامی غیظ و غضب جنم لے گا اس سے خلیفہ کے وہ علوی دشمن فائدہ اٹھا لیں گے جنھوں نے حکومت کے مضافاتی علاقوں میں سراٹھا رکھا ہے۔
طبری کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہےکہ مخالف ومعارض جماعتوں کے ساتھ توازن و اعتدال قائم رکھنے کے لیے خلفاء وسلاطین کے لیے عوام کی حمایت و توجہ حاصل کرنا کتنا ضروری ہوا کرتا تھا۔ یہ ضرورت خاص طور سے اس وقت محسوس ہوتی تھی جب یہ جماعتیں اشتعال میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت حکم راں کو ڈر ہوتا کہ عوام و جمہور کی حمایت اسے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے وہ اس کے دشمن سے جاملیں۔
مذہبی وجوہ سے انجام پانے والی احتجاجی سرگرمیوں میں سے ایک فرعونی سیاست کے خلاف عوام کی مزاحمت بھی تھی۔ اس کی ایک مثال امام ابن الجوزی نے ’المنتظم‘ میں نقل کی ہے کہ 411ھ/ 1021ء میں ’’یہ طے پایا کہ جلال الدولہ (سلطان ابوطاہر البویہی) کے القاب میں’شہنشاہ اعظم‘ کا اضافہ کیا جائے۔ چناں چہ خلیفہ قائم بامر اللہ (م: 467ھ/ 1074ء)نے حکم جاری کر دیا اور خطبوں میں اس کے لیے اس لقب کو استعمال کیا جانے لگا۔ عوام نے اسے ناپسند کیا۔ خطبہ دینے والوں پر انٹیں برسائیں اور ایک فتنہ برپا ہو گیا۔
اسلامی تاریخ میں احتجاج و مظاہرے کا ایک سبب سماجی ہوا کرتا تھا۔ اس قسم کے احتجاج اس وقت ہوا کرتے تھے جب لوگ ایسی چیزوں پر بپھر جایا کرتےتھے جو ان کے طرز حیات کو مکدر کرنے والی یا ان کی سماجی روایات پر ضرب لگانے والی ہوتیں، یا ان کے مذہبی مقدسات و خصوصیات کے خلاف زیادتی یا ان کی حرمت پر مشتمل ہوتیں۔ اس قسم کا مشہور واقعہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں پیش آیا۔ ہوا یہ کہ خلیفہ کی ذاتی فوج کے اندر ترک غلاموں کی خریداری اور اس میں ان کی شمولیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔معتصم کی یہ پالیسی ترک فوجیوں کی تعداد میں اس قدر اضافے کا سبب بنی کہ دارالخلافہ کے باشندے تنگ آ گئے۔ کیوں کہ ’’یہ ترک فوجی اپنے گھوڑوں کو بغداد میں آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے تھے۔ اس مسئلے کو لے کر اہل بغداد اجتماعی شکل میں اس کے پاس پہنچے اور کہا: اگر تم نے اپنی فوج کو ہم سے دور نہیں کیا تو ہم تمھارے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے۔ معتصم نے کہا: مجھ سے کیسے جنگ کرو گے؟ لوگوں نے کہا: سحرگاہی کے تیروں سے (یعنی سحر کے وقت بددعائیں کریں گے)۔ معتصم نے کہا: میرے اندر اس جنگ کی طاقت نہیں ہے۔ یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے شہر ’سُرّ مَن رأی [جس نے دیکھا خوش ہوا] (سامرّاء)) تعمیر کیا گیا اور سیوطی کے مطابق وہ اس شہر کو بغداد کی جگہ دارالحکومت بنا کر وہاں منتقل ہو گیا۔
اسی ضمن میں ابن الجوزی نے ایک واقعہ ا لمنتظم میں نقل کیا ہے کہ 329ھ/941ء میں بغداد کے سیاسی حالات اورامن و امان کی صورت حال اضطراب کا شکار ہو گئی، چناں چہ ’’عوام دارالسلطان میں اکٹھا ہوئے اور دیلمیوں (بویہی فوجیوں) کے ظلم کی شکایت کی کہ یہ لوگ بغیر کرایہ ادا کیے گھروں میں رہنے لگتے ہیں، معاملات میں لوگوں کے ساتھ ظلم وزیادتی کرتے ہیں۔ لیکن سلطان کی طرف سے اس پر کوئی اظہار ناپسندیدگی نہیں ہوا تو عوام نے امام مسجد کو نماز پڑھانے سے روک دیا اور مسجد کے دونوں منبر توڑ دیے۔ دیلمیوں نے انھیں ایسا کرنے سے روکا تو عوام نے ان کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔‘‘
مورخ مقریزی نے ’اتعاظ الحُنفا‘ میں لکھا ہے کہ 387ھ/998ء میں فاطمی کمانڈر امین الدولہ الحسن بن عمار الکُتامی (م: 390ھ/1001ء)نے مصر کے اندر اپنی فوج کو کھلی چھوٹ دے دی، جس کے نتیجےمیں ان کی سرکشی بڑھ گئی اور راستے میں چلنے والی مستورات تک ان کی دست درازیوں سے محفوظ نہیں رہیں۔ یہ لوگ عام لوگوں کے کپڑے تک اتار لیا کرتے۔ لوگوں نے ہنگامہ کیا اور ان کی شکایتیں لے کر حسن بن عمار کے پاس پہنچے، لیکن اس کی طرف سے کوئی ردعمل ظاہر نہیں ہوا۔ پھر یہ صورت حال اس قدر بگڑی کہ ابن عمار کو پہلے اس کے عہدے سے معزول کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔
اہل مصر ابن عمار اور اس کے لشکروں کی زیادتیوں سے باہر نکلے ہی تھے کہ فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ (م: 411ھ/1021ء) کے غیر دانش مندانہ اور غیر مستقل فیصلوں کے بھنور میں پھنس گئے۔ اس کے ان فیصلوں کی وجہ سے فاطمی جاسوسی نظام کو معاشرے کی نجی زندگیوں میں حد سے زیادہ دخیل ہونے کا موقع مل گیا اور اس کے جاسوس گھروں کے اندر کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہونےلگے۔
ایسے ہی فیصلوں میں سے ایک وہ تھا جس کا ذکر ابن الجوزی نے ’المنتظم‘ میں کیا ہے کہ 405ھ/1015ء میں اس نے ہر شاہراہ پر جاسوس متعین کر دیے۔ یہ جاسوس ایک ایک بات سے اسے مطلع کیا کرتے۔ بوڑھی عورتوں کو متعین کیا جو گھروں میں گھس کر عورتوں سے باتیں لیتی اور اس تک پہنچایا کرتی تھیں، مثلاً فلاں شخص فلاں عورت سے اور فلاں عورت فلاں شخص سے محبت کرتی ہے۔ یہ لوگ ایسی ایسی باتیں بھی اس تک پہنچایا کرتے تھے۔ پھر وہ کارندوں کو بھیج کرایسی عورتوں کو گرفتار کرا لیا کرتا تھا۔ کچھ عورتیں جمع ہو جاتیں تو انھیں پانی میں غرق کرنے کا حکم دیتا تھا۔ لوگ اس حرکت سے تنگ آ گئے اور مختلف طریقوں سے احتجاج کیا۔ (جاری)