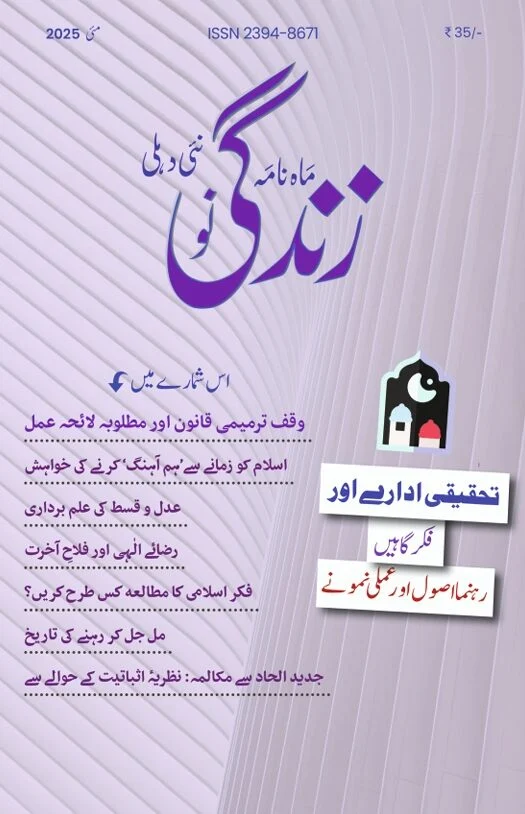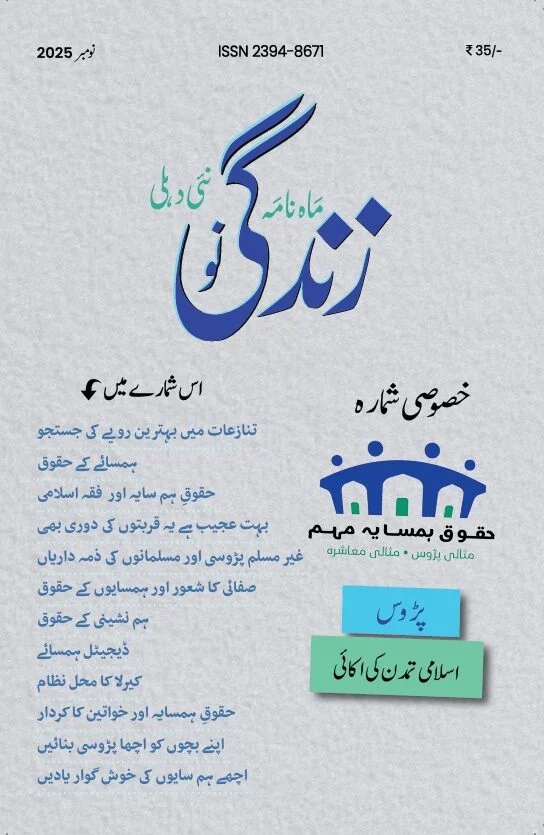فلاحی اداروں کے ذریعے اسلام کی عملی شہادت کے مرکزی موضوع کے تحت آج ہم اُن اداروں کو زیر بحث لائیں گے جن کا مقصد علمی تحقیقات اور فیصلہ سازی و پالیسی سازی میں علمی معاونت ہے۔یعنی تحقیقی ادارے (research centres) اور فکر گاہیں (think tanks)۔ تحقیقی اداروں سے ہماری مراد وہ ادارے ہیں جوعلم کے مختلف شعبوں میں نئے علوم کی پیداوار knowledge production) )کا کام کرتے ہیں اور فکر گاہوں (think tanks) سے مراد وہ ادارے ہیں جو سرکاروں ، تنظیموں، قیادتوں ،تجارتوں کو اور دیگر اہم فیصلہ سازوں کو علمی مشاورت فراہم کرتے ہیں، یعنی پالیسیوں کی تشکیل و ترمیم ، حکمت عملی کی تعیین اور بڑی فیصلہ سازی میں علمی کمک بہم پہنچاتے ہیں۔
اسلامی تحریک بنیادی طور پر ایک فکری و نظریاتی تحریک ہے اوراس کے پیش نظر ایک متبادل تمدن کی صورت گری اور اس کی تشکیل اور اس کا ارتقا ہے۔ اس لیے ان دونوں طرح کے اداروں کی اس کے لئے بڑی اہمیت ہے۔ اس سلسلہ مضامین میں اختیار کردہ طریقِ کار کے مطابق پہلے ہم اس حوالے سے اسلام کے بنیادی اصولوں یا اساسی قدروں (core values)کو پیش کریں گے، پھر اسلامی تہذیبی روایات کے حوالوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری تاریخ کے روشن ادوار میں ان اداروں کے کام کا طریقہ کیا رہا اور انھوں نے کیسے اسلام کی قدروں کا عملی نمونہ پیش کیا ۔ آخر میں ہمارے زمانے میں ان اداروں کے مطلوبہ کردار کے سلسلےمیں کچھ گذارشات پیش کی جائیں گی۔
اساسی اقدار
تحقیقی اداروں اور فکر گاہوں کے لیے اسلام کی درج ذیل تعلیمات اساسی اقدارکی حیثیت رکھتی ہیں:
۱۔ علم کی اہمیت اور رائے سازی و فیصلہ سازی کے لیے ٹھوس علم اور تحقیق کی اساسیت : علمی تحقیقات اور علوم کی پیداوار و افزائش قرآن مجید کی اہم تعلیمات میں شامل ہے۔ کسی بھی معاملے میں رائے تک پہنچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے اسلام نے ٹھوس علم اور تحقیق کو ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے حساس امور و معاملات میں رائے قائم کرنے سے پہلے سنجیدہ تحقیق کا واضح حکم دیا ہے۔ ( یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ الحجرات6)
قرآن مجید کس قسم کا نظریاتی ڈسکورس چاہتا ہے اس کی وضاحت اُن مطالبات سے ہوتی ہے جو اس نے اپنی دعوت کے مخالفین سے بار بار کیے ہیں، یعنی منطقی دلیل کا مطالبہ (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ۔کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو ۔النمل: 64)،مشاہداتی شہادت کا مطالبہ (وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ۔ انھوں نے فرشتوں کو، جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں، عورتیں قرار دے لیا۔ کیا اُن کے جسم کی ساخت انھوں نے دیکھی ہے؟ الزخرف:19) اور دستاویزی ثبوت کا مطالبہ(ائْتُونِی بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ۔ اِس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ (باقی ماندہ حصہ)،(اِن عقائد کے ثبوت میں) تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ الاحقاف:4)۔
اس سلسلے میں اہم رہنمائی قرآن مجید کی ایک اہم ترکیب ‘قول بأفواہ ‘سے ہوتی ہے۔افواہ ، فم کی جمع ہے جس کےمعنی منہ کے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی ؒفرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی قول کی نسبت فم کی طرف کی کی گئی ہے(منہ کی باتیں) وہاں مراددروغ گوئی ہے۔ ایسی باتیں جو منہ سے تو کہہ دی جاتی ہیں لیکن قلب و ضمیر ان کا ساتھ نہیں دیتے۔[1] یعنی اس کا معنی تقریباً وہی ہے جس کے لیے ہم ان دنوں جعلی خبریں (fake news)، غلط اطلاعات (misinformation)، فریبی بیانیے (deceptive narratives) اورجھوٹے علوم (pseudoscience) جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو پھیلانے اور ان کو رائے یا فیصلے کی بنیاد بنانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے بعض تصورات پر سخت گرفت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ ‘افواہوں’ پر اپنے افکار تشکیل دیتے ہیں:(ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ یضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ یؤْفَكُونَ۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں اُن لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار اِن پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھارہے ہیں۔توبہ:۳۰) اسی طرح اہل ایمان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ بغیر ٹھوس تحقیق اور علم کے محض افواہوں کو اپنی آرا کے لیے بنیاد نہ بنائیں: (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَیسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَینًا وَهُوَ عِندَ اللَّـهِ عَظِیمٌ ۔خیال کرو جب تم اپنی زبانوں سے وہ بات نقل کر رہے تھے اور اپنے مونہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کی بابت تمہیں کوئی علم نہیں تھا! اور تم اس کو معمولی بات خیال کر رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ النور: ۱۵) نبی کریم ﷺ کی مشہور حدیث ہے: (كَفَی بِالْمَرْءِ كَذِبًا، أَنْ یحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات آگےبیان کر دے)[2]۔قرآن نے وضاحت کے ساتھ یہ حکم بھی دیا ہے کہ علم و تحقیق کے بغیر کسی بات کے پیچھے پڑنا اہل اسلام کے شایان شان نہیں ہے۔( وَلَا تَقْفُ مَا لَیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا(کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً سماعت، بصارت اور عقل، سب ہی کی باز پرس ہونی ہے۔الاسراء 36)سید قطبؒ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں:
” قرآن کریم یہ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قبل پوری تحقیق کرو، معاملے کو پایہ ثبوت تک پہنچاؤ۔ یہ اسلام کا نہایت ہی باریک طریق کار ہے۔ جب دل و دماغ اس منہاج پر گامزن ہوجائیں تو پھرو ہم و گمان کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی اور معاملات نیز فیصلوں کا مدار تحقیق و ثبوت پر ہوتا ہے ، مفروضوں پر نہیں۔ انسانیت کو یہ علمی اور سائنسی انداز سب سے پہلے قرآن نے دیا ہے۔۔۔ ایک مسلمان اپنی سوچ ، اپنے تصور ، اپنے شعور ، اپنے فیصلوں میں پختہ ثبوت اور یقین کا قائل ہوتا ہے ، وہ کوئی بات ، کوئی روایت ، کوئی حکم اور کوئی فیصلہ بغیر شہادت اور ثبوت کے نہیں مانتا، جب تک اس کے تمام اجزا پایۂ ثبوت و یقین تک پہنچ نہ جائیں۔“[3]
اس رویے کا ایک اہم مظہر اسلام کا تصور حکمت ہے۔ قرآن مجیدمیں حکمت کاذکر کثرت سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (یُؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ یَّشَآءُۚ وَمَنْ یُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِیَ خَیْرًا كَثِیْرًا وَمَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَاب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی ، اُسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔البقرة: 269)حکمت کی تعریف میں علمائے اسلام نے جو باتیں لکھی ہیں ان سے لگ بھگ وہی معنی متعین ہوتے ہیں جو اس مضمون میں زیر بحث ہیں،یعنی ٹھوس علم اور تحقیق کے ذریعے درست ترین نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت۔ بطور مثال حکمت کے سلسلے میں درج ذیل بیانات ملاحظہ ہوں:
علم اور عقل کے ذریعے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت(امام راغب الاصفہانیؒ)[4] صحیح وقت پر،صحیح طریقے سے، صحیح عمل کو جاننے اور اختیار کرنے کی صلاحیت( امام ابن قیمؒ)[5]،لاعلمی اورغلطی سے بچ کر قول وعمل میں بالکل درست رویہ اختیار کرنے کی صلاحیت (امام رازیؒ) [6] ذکاوت جس سے دین و دنیا کی مصلحتوں کا فہم حاصل ہوتا ہے، وحی ، عقل اور علوم کے ذریعے صحیح نتیجے اور فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت(شاہ ولی اللہؒ)[7]، وہ قوت و صلاحیت کہ جس سے انسان معاملات کا فیصلہ حق کے مطابق کرتا ہے(امام فراہیؒ)[8]، صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ[9] (مولانا مودودیؒ)،نفع بخش علوم، عقلِ راجح، فہمِ ثاقب اور اقوال و افعال میں صائب الرائے ہونا (لقمان سلفیؒ)[10] ان سب تشریحات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فیصلوں کا حکمت پر مبنی ہونا مقصود ہے اور حکمت شریعت اسلامی اور انسانی علم و تجربے ، دونوں کی اساس پر درست اور متوازن فیصلے کا نام ہے۔
گویا فیصلے اور رائے کو ٹھوس علم اور تحقیق کی اساس پر استوار کرنا، اور گمان، اٹکل، توہمات، بے بنیاد اندازوں وغیرہ کی بنیاد پر رائے قائم کرنے سے گریز کرنا، اسلام کی اہم قدر ہے۔ یہ قدر اسلامی معاشروں اور مسلمانوں کی مختلف سطحوں کی فیصلہ سازی کے لیے تحقیقی اداروں اور فکر گاہوں کو ضروری اور ناگزیر بنادیتی ہے۔
۲۔اسلام کے عقیدے کےمطابق اور اسلامی شریعت کےمقاصد کے تحت موجودہ علوم کی تشکیل نو اور نئے علوم کی افزائش :جب معاملات کو علم و تحقیق کی اساس پر استوار کرنا ہے تو اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود علم و تحقیق کیا ہے؟ اس حوالے سے اسلامی فلسفہ علم (epistemology)کا پہلا اصول ، جسے اسلامی مراکز تحقیق اور فکر گاہوں کے لیے رہنما اصول ہونا چاہیے، یہ ہے کہ علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بہت چھوٹا سا حصہ محض اپنے فضل و کرم سے انسان کو عطا کیا ہے۔ (یعْلَمُ مَا بَینَ أَیدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا یحِیطُونَ بِشَیءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اُن سے اوجھل ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے اور اُس کی معلومات میں سے کوئی چیز اُن کی گرفت ادراک میں نہیں آسکتی الّا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی اُن کو دینا چاہے ۔البقرة: 255) انسان کو جو علم بھی ملاہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا ہی سے ملا ہے ۔(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لیے سماعت بصارت اور عقل بنائی تاکہ تم شکر کرو۔النحل: 78) اور جو کچھ علم انسان کو ملا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔( وَمَا أُوتِیتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا۔ اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ الاسراء: 85)
اس لیے علم و تحقیق کے راستے کا سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم اسی علم حقیقی سےاستفادہ ہے۔ اسلامی تحقیقی ادارے اور فکر گاہیں مسائل کے حل اور بہتر آرا کی تلاش میں سب سے پہلے اس علم حقیقی سے رجوع کریں گی۔ اس کا پہلا سرچشمہ وحی الہی ہے۔ جو اللہ کے کلام اور اس کے نبی ﷺ کی سنت دونوں پر مشتمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کی مذمت کی ہے جو وحی الہی کو چھوڑ کر اپنے خود ساختہ علوم میں مگن رہتے ہیں۔( فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ۔جب ان کے رسُول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اُسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا۔غافر: 83)اس آیت کی تشریح میں مولانا مودودیؒ فرماتےہیں:
“یعنی اپنے فلسفے اور سائنس، اپنے قانون، اپنے دنیوی علوم اور اپنے پیشواؤں کے گڑھے ہوئے مذہبی افسانوں (Mythology) اور دینیات (Theology) ہی کو انھوں نے اصل علم سمجھا اور انبیا (علیہم السلام) کے لائے ہوئے علم کو ہیچ سمجھ کر اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔”[11]
وحی الہی کے بعد، اللہ تعالیٰ کے علم سے ممکنہ استفادے کی ایک اور شکل جو قرآن بتاتا ہے وہ اللہ کی آیات میں غور وفکر ہے۔ قرآن نے آفاق و انفس اور اللہ کی مخلوقات میں غور و تدبرکی دعوت بھی دی ہے اور اس طرح کے غور و تدبر کو علم کا سرچشمہ بھی قرار دیا ہے۔(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا یخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اُس سے ڈرتے ہیں۔فاطر: 27اور28) ۔ اس غور وفکر سے طبعی سائنس (natural science)میں دریافت و ایجاد کی راہیں ہم وار ہوتی ہیں ۔موجودہ ٹکنالوجی کے اکثر کرشمے مظاہر فطرت پر غور وفکر اور اس کی نقالی ہی کے نتائج ہیں۔[12]اسی طرح قرآن نے انسانی تاریخ اور انسانی رویوں کے اچھے اور برے نتائج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ (فَهَلْ ینظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِینَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِیلًا۔ اب کیا یہ لوگ اِس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی اِن کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔فاطر:43) اللہ کی سنت پر اس طرح کے غور وفکر سے مختلف سماجی علوم میں تحقیق کے لیے راہیں ہم وار ہوتی ہیں اور تحقیقات کےلیے سمت اور رہنمائی میسر آتی ہے۔
اس طرح تحقیق و ریسرچ کا پہلا مرحلہ وحی الہی اور سنت رسول سے رہنمائی کا حصول ہے اور دوسرا مرحلہ آفاق وانفس کی نشانیوں اور انسانی رویوں اور ان کے عواقب و نتائج کا معروضی مطالعہ ہے۔ اس وقت اسلامی فلسفہ علم (islamic epistemology)پر تفصیلی بحث مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہ اشارہ مقصود ہے کہ اسلامی تحقیقی اداروں اور فکر گاہوں کا اصل امتیاز اسلام کے مخصوص فلسفہ علم اور اس کے نتیجےمیں تشکیل پانے والے طریق کار (methodology)کی اتباع ہے۔
۳۔ مصلحت اور نافعیت: تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ تحقیق اور افزائشِ علم بے مقصد نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مقصد انسانوں کو فائدہ پہنچانا اور ان کی مصلحت کی تحصیل ہونا چاہیے۔ قرآ ن مجید نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو ایسے علوم سیکھتے اور سکھاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ۔ (وَیتَعَلَّمُونَ مَا یضُرُّهُمْ وَلَا ینفَعُهُمْ۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لئے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتیں ۔البقرة: 102) رسول اللہ ﷺ نے غیر نافع علم سے پناہ مانگی ہے۔( اللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنْ الأربع من علم لا ینفع۔۔ اے اللہ میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔(پہلی چیز) ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔)[13] ہمارے علما نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی شریعت کا مقصد ہی انسان کوفائدہ پہنچانا ہے۔امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ شریعت آئی ہی اس لیے ہے کہ مصالح (یعنی انسانوں کے لیے مفید امور) کی تحصیل و تکمیل ہو اور مفاسد کی روک تھام ہو یا انہیں کم کیا جاسکے۔[14]
یہ اسلام کابہت اہم اصول ہے۔ مصلحت میں بھی عوامی مصلحت (public good)کو فوقیت حاصل ہے۔ شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ (المصلحة العامة مقدمة علی المصلحة الخاصة۔[15]مصلحت عام یعنی اجتماعی مصلحت ، مصلحت خاص یعنی ایک فرد یا چند افراد کی مصلحت پر مقدم ہوگی۔) اس اصول سے علم و تحقیق کے سلسلےمیں بھی اہم رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ تحقیق اور علمی ترقیوں کے پیش نظر اہم مقصد زیادہ سےزیادہ لوگوں کی منفعت اور ان کی راحت رسانی ہونا چاہیے۔معاصر دنیا میں علوم و فنون اور ٹکنالوجی کی منفعت پرستی(profiteering)صارفیت پسندی و اشرافیہ پسندی(elitist and consumerist technology)اورقوم پرستی ومفاد پرستی (militocratic technology) بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ٹکنالوجی کی بے پناہ قوت عوامی بہبود کے لیے استعمال نہیں ہوپارہی ہے۔ اسلامی تصور کے مطابق یہ سخت نامطلوب کیفیت ہے اور مصالح عام پرمرکوز علوم (science for the common good)اسلام کا مطمح نظر ہے۔[16]
یقیناً موجودہ زمانے میں جن ٹھوس باتوں کو ‹علم›یا تحقیق کہا جاتا ہے،ان کی نافع اور غیر نافع میں تقسیم بھی اکثر دشوار ہوتی ہے۔ علم ایک ایسے ہتھیار کے روپ میں سامنے آتا ہے جو چاقو بن کر کچن کی بنیاد ی ضرورت بھی بن سکتا ہے اور کسی پیشہ ور قاتل کے ہاتھوں میں پہنچ کر تباہی کا آلہ بھی۔ لیکن علم کے اطلاقی پہلو (applied science)اور تفصیلی تحقیق کاجب مرحلہ آتا ہے تو یہ سوال ضرور درپیش ہوتا ہے کہ اس تحقیق کا کیا فائدہ ممکن ہے اور فائدہ اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں؟
۴۔معاصر علوم و فنون اور اہل علم واہل تخصص سے استفادہ:مصلحت و منفعت اور نفع رسانی کے بہتر سے بہتر طریقوں کی تلاش میں اسلام جہاں اپنے متبعین کو غور و فکر اور تحقیق و دریافت کی صلاحیتوں سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کی ترغیب دیتا ہے وہیں یہ ترغیب بھی دیتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، موجود معاصر علوم اور ماہرین و اہل تخصص سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ قرآن مجید کی آیات (فَسْئَلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ سو اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہلِ علم سے پوچھ لو۔النحل:16) (فَاسْأَلْ بِهِ خَبِیرًا۔ اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔الفرقان: 59) وغیرہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہ عمومی اصول بھی بیان کیا ہے کہ جن امور میں ضرورت ہو وہاں اہل علم سے معلومات لی جائیں۔[17] نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ (الكَلِمَةُ الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، فَحَیثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ۔ حکمت و دانائی کی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، جہاں بھی اس کو پائے وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے)[18] شیعہ مصادر میں حضرت علیؓ سے منسوب قول ملتا ہے کہ ( الحكمة ضالة المؤمن، فاطلبوها ولو عند المشرك، تكونوا أحق بها وأهلها۔[19] حکمت مومن کی متاع گم شدہ ہے۔ اسے حاصل کرو، چاہے وہ مشرک ہی سے کیوں نہ ملے، اس پر تمہارا یعنی اہل ایمان کا زیادہ حق ہے۔) بلکہ ان مصادرکے مطابق تو حضرت علیؓ نے حکمت کی بات قبول نہ کرپانے کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔[20] نبی کریم ﷺ کے اسوے سے بھی اس اصول کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ نے غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی ؓکی تجویز پر ایک ایسا طریقہ (خندق کی کھدائی) اختیار کیا تھا جو ایک اجنبی قوم کا طریقہ تھا اور اس وقت کے مسلمان اور غیر مسلم عرب،سبھی اس سے نامانوس تھے۔[21] طائف کے ایک طبیب حارث بن کلدہ (جونیشاپور کی اکیڈمی میں استاد رہے، ایران اور دیگر ممالک میں طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ، بادشاہوں تک کا علاج کیا ، طب پر کتابیں لکھیں اور عرب کے سب سے بڑے طبیب مانے جاتے تھے[22] رسول اللہ ﷺ نے طائف کی فتح کے بعد نہ صرف انھیں معافی دی، بلکہ عزت و احترام کے ساتھ انہیں مدینہ منورہ میں جگہ دی۔[23]جب حضرت سعد بن ابی وقاص ؓکو دل کا عارضہ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے انھیں حارث بن کلدہ کے پاس جاکر علاج کرانے کا حکم دیا۔[24] رسول اللہ ﷺ نے دوسری طرف حساس معاملات میں بغیر ضروری مہارت کے مداخلت اور اپنے ناقص مشوروں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی سختی سے ہمت شکنی کی ہے۔(من تطبب ولا یعلم منه طب فهو ضامن۔ جو علم طب نہیں جانتا پھر بھی کسی کا علاج کرے تو نقصان کی صورت میں وہ ذمے دار ہوگا۔) [25]زراعت، سپہ گری، صنعت وحرفت، زبان دانی و ادب، وغیرہ جیسے دسیوں امور ہیں جن کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے ماہرانہ مشوروں کی ہمت افزائی کی اور خود بھی ان سے استفادہ فرمایا۔ [26]
۵۔ مشاورت اور اجتماعی غور وفکر:پانچواں اہم رہنمااصول یہ ہے کہ اجتماعی امور میں تحقیق اور بہتر فیصلہ سازی اجتماعی غور و فکر اور شورائی طریقوں سے ہونی چاہیے۔ اسلام نے اجتماعیت کو غیر معمولی اہمیت دی ہے۔ عبادتوں تک میں اجتماعیت کو شامل رکھا ہے۔ اجتماعی آفات اورخطروں پر (سورج گرہن، چاند گرہن، استسقا، دشمن کا خطرہ وغیرہ) دعاؤں کے اہتمام تک کے لیے اجتماعی طریقے سکھائے گئے ہیں۔ اہل امرکویہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے شورائی طریقوں سے کریں۔یہ حکم قرآن مجید میں دو بار آیا ہے۔ (وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر۔ اور ان سے (اہم) معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔آل عمران: 159) اور (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَینَهُمْ۔ اور ان کا (ہر) کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے ۔ سورہ شوریٰ: 38)نبی کریمﷺ رسول ہونے کے باوجود اہم معاملات مشورے سے فیصل فرماتے تھے۔حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں: (مَا رَأَیتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ ۔ میں نے رسول اللہ سے زیادہ اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا)[27] غزوہ بدر اوراحد کے موقعوں پرآپ نے عام مشورہ فرمایا۔ بعض موقعوں پر اکابر صحابہ کو مشورے کے لیے طلب فرمایا اور ہوازن کےمال غنیمت اور قیدیوں کے مسئلے پر آپ نے قبیلوں کے سرداروں سے یعنی لوگوں کے نمائندوں کو طلب کرکے ان سے مشاورت فرمائی۔ [28]
علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں ابن عطیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:
“اصحاب امر جن امورکاعلم نہیں رکھتے ان میں اُن پر اہل علم سے مشورہ کرنا واجب ہے اور(علمائے دین سے) جن امور دین میں انہیں مشکل در پیش ہو اور جنگ سے متعلق معاملات میں فوجی ماہرین سے اورجن امور کا تعلق عوامی مصالح سے ہو ان میں عوام کے نمائندوں سے، اور جو امورشہروں اور ان کے مصالح سے متعلق ہو ان میں وہاں کے عمال اور ذمے داروں سے۔”[29]
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ محض ایک میکانکی عمل کانام نہیں ہے بلکہ اسلامی معاشرے میں مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ شورائیت کا کلچر مطلوب ہے۔ مشورہ ان لوگوں سے بھی مطلوب ہے جو معاملے سے متعلق (stake holders)ہیں اور ان لوگوں سے بھی مطلوب ہے جو مشورہ طلب مسئلے کے ماہرین اور اہل تخصص ہیں۔ماہرین اور اہل تخصص کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ باہم مشورے، تبادلہ خیال اور اجتماعی غور وفکر سے بہتر رائے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
کچھ عملی نمونے اسلامی تاریخ سے
ان اصولوں کو اسلامی تاریخ میں کیسے برتا گیا اس کو واضح کرنے کے لیے ہم ذیل میں کچھ مثالیں پیش کررہے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع علمی اداروں یا تحقیق و دریافت کی منظم اجتماعی کوششوں سے متعلق ہے اس لیے یہاں صرف ادارہ جاتی کوششوں کا ذکر کیا جارہا ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ ہر اہم کام اور فیصلے کے لیے ٹھوس علم، سنجیدہ تحقیق اور گہری ریسرچ کو بنیاد بنایا گیا۔ قرآن و سنت کی اساس پر علوم کو نیا رخ دیا گیا۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی مخصوص ضرورتوں کی تکمیل کی خاطر اور اسلامی تصورات کے مطابق بالکل نئے علوم تخلیق کیے گئے۔ علوم کی تخلیق و تشکیل نو کے اس عمل کے لیے آزادانہ غور وفکر کی فضا کو پروان چڑھایا گیا۔ مختلف دینی اور معاصر علوم کے امتزاج، تال میل اور بین تخصصی (interdisciplinary)تحقیقات کی ہمت افزائی کی گئی اور جاہلی تمدنوں کے معاصر علوم سے بھی اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں بھرپور استفادہ کیا گیا۔
امام ابوحنیفہؒ کی تدوین فقہ اور بعد کے فقہی ادارے
اس سے قبل ہم عرض کرچکے ہیں کہ آزاد تھنک ٹینک کا عملی نمونہ دور اول کی تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی تدوین فقہ کی مجلس ہے۔ شرعی احکام میں رائے قائم کرنے کے لیے اجتماعی غور وفکر کاطریقہ خلفائے راشدین کے زمانےہی سے جاری تھا ۔ حضرت عمر ؓکے بہت سے اجتہادات اسی طریقے سے ہوئے تھے۔[30]امام ابوحنیفہ کے زمانے کے آتے آتے اس عمل میں ایک طرح کی باقاعدگی پیدا ہوگئی تھی۔ چنانچہ حرمین میں فقہائے سبعہ (زید بن ثابت ؓکے بیٹےخارجہ، حضرت ابوبکرؓ کے پوتے قاسم، عروہ بن زبیر، عتبہ بن مسعود کے پوتے عبید اللہ،سعیدبن المسیب، ام المومنین میمونہ ؓکے آزاد کردہ غلام سلیمان بن یسار اور عبد الرحمن بن عوفؓ کے بیٹے ابوسلمہ رحمہم اللہ تعالیٰ) کی مجلس کو ایک طرح کی اتھاریٹی حاصل تھی۔[31]حکمرانوں اور قاضیوں کے سامنے جومسائل آتے وہ اس سات رکنی مجلس کے سامنے پیش ہوتے اور انھی کے اجتماعی فیصلے کے مطابق عمل ہوتا۔ امام ابوحنیفہ نے حرمین میں قیام کے دوران اس اجتماعی طریق کار کی برکتوں کو قریب سے دیکھا۔ اسلامی حکومت تیزی سے وسعت اختیار کرتی جارہی تھی اور صحابہ کے بعد تابعین بھی تیزی سے رخصت ہوتے جارہے تھے ۔ اس لیے باقاعدہ طور پر مدون فقہ کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ امام ابوحنیفہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اسے بہت ہی منظم اور باقاعدہ ادارہ جاتی شکل دے دی۔ امام ابوحنیفہ کی اس مجلس کی درج ذیل خصوصیات خاص طور پر قابل ذکرہیں۔
۱۔ تحقیق و ریسرچ کے معاملے میں سچی اور بے لاگ حق پسندی، تقویٰ اور دیانت داری اس مجلس کی اہم ترین خصوصیت تھی۔ امام صاحبؒ کے سوانح نگاروں نے اُس تقویٰ، احتیاط ، خوف خدا وغیرہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو امام ابوحنیفہ اوران کے شاگردوں کی نمایاں خصوصیت تھی اور جس نے ان کی تحقیقات کو اعتبار بخشا تھا۔ [32]امام ابوحنیفہؒ کو اور ان کے شاگردوں کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف سازشیں کی گئیں ،گھناؤنے الزامات لگائے گئے۔ طوائف کوان کے پاس بھیج کر اس کے ساتھ رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا ڈرامہ رچا گیا ، جیل بھیجا گیا، ان کو مردود الشہادت (ایساشخص جس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوسکتی) ڈکلیر کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔[33]حکومت نے ظلم کا نشانہ بنایا اور قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا۔
لیکن ان تمام مرحلوں میں جس بے لاگ حق پسندی اور اظہار حق کا امام صاحب اور ان کے شاگردوں نے مظاہرہ کیا وہ ان کے کردار کا بہت ہی درخشندہ پہلو ہے اور اسلامی تحقیقات اور اسلامی فکر گاہوں اور تحقیقی اداروں کی سب سے اہم خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔[34]یعنی اخلاص، خدا کی خوشنودی کوہر حال میں مقدم رکھنا، نہ عوام میں نامقبول ہوجانے کی پروا کرنا، نہ دین داری کے دعوے دار حلقوں کی ناپسندیدگی کو خاطر میں لانا اور نہ حکمرانوں سے ڈرنا بلکہ جو بات سچ محسوس ہو اسے بلاخوف لومت لائم بیان کرنا۔
۲۔ امام صاحب ؒکی اس مجلس کی دوسری اہم خصوصیت کھلے بحث و مباحثے کے اجتماعی طریقے سے رائے قائم کرنے کامنہج تھا۔ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ امام صاحب کی تدوین فقہ کی اس مجلس میں اجتماعی غور و فکر کی کئی سطحیں تھیں۔ امام صاحب کے حلقے کے جملہ ارکان لگ بھگ ایک ہزار کے قریب تھے۔ یہ سب غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے حامل اور مختلف علوم و فنون کے ماہر لوگ تھے جن سے حسب ضرورت استفادہ کیا جاتا تھا۔[35]ان میں سے چالیس افراد کو منتخب کرکے امام صاحب نے اصل مجلس بحث تشکیل فرمائی تھی۔[36]ان چالیس میں گیارہ افراد پر مشتمل ایک اور مجلس تھی جو مباحث کی روشنی میں فقہ کی تدوین کا کام کرتی تھی۔[37] پھر ان میں بھی چار افرادپر مشتمل خاص الخاص مجلس چہارگانہ تھی جن کے درمیان اتفاق رائے اہم مسائل کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔[38]جو مسائل آتے ان پر ان مجالس میں سیر حاصل گفتگو ہوتی۔ بعض اوقات ایک ہی مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے کئی کئی دن بحث ہوتی ۔[39] بحث کے بعد جو نتیجہ نکلتا اسے امام ابویوسف لکھ لیتے اور طے شدہ بات سے کسی شریک مجلس کو اختلاف ہوتا تو اس کا اختلاف بھی درج فرمالیتے۔[40]اس طرح تحقیق و ریسرچ کا یہ ایک باقاعدہ منظم ادارہ جاتی نظام تھا۔
۳۔ اس مجلس میں بحث و گفتگو اور نقد و تبصرے کی جو آزادی تھی اور جس بے تکلف ماحول میں چھوٹے بڑے مل کر تحقیق یعنی حق کی تلاش کرتے ،اس کی یہ خصوصیت بھی اسلام کے مزاج کی نمائندہ اور اس کی عملی شہادت تھی۔جرجانیؒ کی روایت امام ابوحنیفہ کے اکثر سوانح نگاروں نے نقل کی ہے کہ ایک دفعہ وہ امام ابو حنیفہؒ کی مجلس دیکھنے کے لیے گئے۔ امام صاحب نے ایک مسئلے میں اپنی رائے بیان کی تو ایک کم عمر نوجوان کھڑا ہوگیااور کہا کہ آپ کی بات غلط ہے۔جرجانی کو بڑی حیرت ہوئی ۔ انھوں نے شرکائے مجلس کو ڈانٹ پلائی کہ تمہیں کیا ہوگیا ہے، اپنے اتنے عظیم استاد سے اس طرح بات کرتے ہو؟ امام ابوحنیفہ ؒ نے مداخلت فرمائی اور فرمایاکہ نحن عودناہ۔ ان کو یہ عادت ہم نے خودڈالی ہے۔[41] (علم و تحقیق کے لیے اسی طرح کی آزادانہ گفتگو ضروری ہے۔ ) سلف پرستی اور اکابر پرستی سے آزاد ہوکر رائے قائم کرنے کا جو مزاج امام صاحب ؒنے پیدا کیا تھااس کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوسکتی ہے کہ آج جو فقہ، فقہ حنفی کہلاتی ہے اس میں بہت سی آرا امام ابوحنیفہ کی رائے سے مختلف ہیں۔ متعدد امور ہیں جن میں ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا اور امام صاحب کے مقابلے میں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے فقہ حنفی کا جزو بنی اور بعض امور ایسے بھی ہیں جن میں بعد کے ادوار کے فقہا کی رائے مفتی ٰبہ کہلائی ۔[42]قرآن وسنت کو اساس بناکر آزادانہ غور و فکراور اکابر اور مسالک و مکاتب کے بانیوں کے افکار میں ارتقا ، اسلام کی علمی روایت کی اہم خصوصیت رہی ہے۔ (اب مسلمانوں میں یہ روایت بری طرح پامال ہے)
۴۔ امام صاحب ؒکے اس تھنک ٹینک کی ایک اور اہم خصوصیت اس کا کثیرالعلومی(multidisciplinary)مزاج تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ ؒکی تحقیق کے مطابق امام صاحب کی اس مجلس میں قرآن و حدیث کے ماہرین ہی نہیں بلکہ لغت، صرف و نحو، تاریخ، حیاتیات و نباتیات، کیمیا، جغرافیہ و ہئیت، کاروبار و تجارت، آب پاشی و غیرہ متعدد علوم کے ماہر ترین افراد موجود تھے جو زیر غور مسائل میں مددکرتے۔[43]مشہورمحدث وکیع بن الجراح (جو امام شافعیؒ اور امام احمدبن حنبلؒ کے استاذ تھے) کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ امام ابوحنیفہ نے فلاں مسئلے میں غلطی کی ہے تو وکیع ؒنے امام صاحبؒ کی اسی کثیرالعلومی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ:
”اس شخص کے پاس قیاس و رائے میں ابویوسف اور زفر ہوں ، حدیث میں یحییٰ بن زائدہ ،حفص بن غیاث ،حبان اور مندل ہوں، لغت وزبان میں قاسم بن معن اور زہدوتقویٰ میں داود الطائی او ر فضیل بن عیاض جیسے لوگ ہوں،وہ کیسے غلطی کرے گا؟ اور غلطی کرے گا بھی تو (اتنے سارے ماہرین) اسے کیسے غلطی پر قائم رہنے دیں گے۔“ [44]
استفادے اور بحث و مباحثے کا یہ معاملہ صرف اسی مجلس تک محدود نہیں تھا بلکہ جب کوئی اہم مسئلہ زیربحث ہوتا تو دوسرے علمی حلقوں سے اور محدثین و اہل علم سے مراجعت کی جاتی۔ مجلس کے بعض ارکان کے ذمے ، جن میں نمایاں نام ابو یوسف کا تھا ،یہ مستقل کام تھا کہ زیر بحث مسئلے پرمختلف محدثین سے روایات اور ان کی آرا جمع کریں اور اسے مجلس میں پیش کریں۔[45]
ڈاکٹر حمید اللہؒ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ امام صاحب ؒنے حسب ضرورت بیرونی مصادر(یعنی فارس، روم وغیرہ کے قوانین) سے بھی استفادہ کیاہے۔مستشرقین نے حنفی فقہ پر یہ نامعقول اعتراض کیا تھا کہ یہ رومی قانون کا چربہ ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ ؒنے محکم دلائل کے ساتھ جہاں اس الزام کا بے بنیاد اور حد درجہ نامعقول ہونا ثابت کیا ہے وہیں یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اسلام کی اسپرٹ کے مطابق قرآن و سنت کی رہنمائی کے تابع رہ کر اس فقہ نے دنیا بھر کے نافع عناصر سے ضرور فائدہ اٹھایا ہے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں بلکہ عین مطلوب ہے۔[46]
امام موصوفؒ کے اس نمونے نے بعد کے ادوار میں بھی خاص طور پرفقہ کے میدان میں اس طرح کی ادارہ جاتی تحقیق کی روایت قائم کی۔ تاریخ میں اس حوالے سے دو کام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک مغلیہ عہد میں فتاویٰ عالم گیری کی تدوین ہے۔ ساڑھے تین سو سال پہلے اورنگ زیب عالم گیرؒ نے اس کی تدوین کے لیے پچاس سے زیادہ منتخب علما کی ٹیم تشکیل دی تھی جو کئی ذیلی شعبوں میں منقسم تھے اور ہر شعبے میں معاونین اور اسٹاف کی وافر سہولیات فراہم کی گئی تھیں۔ اس زمانےمیں اس منصوبے کا بجٹ دس لاکھ روپیے (موجودہ قیمتوں کے اعتبار سے تقریباً پانچ سوکروڑ روپیے) تھا۔[47]
دوسراعثمانی عہد کے آخر میں قواعد فقہ کی تدوین کا کام ہےجس کے نتیجے میں مشہور ‘‘مجلة الاحکام العدلیة’’ مدون ہوا جس کے ذریعے شرعی قوانین کو جدید طرز پر مجموعہ قوانین کی شکل میں مدون (codify)کیا گیا اور فقہ کے ننانوے ایسے اصول مدون کیے گئے جن سے قیاس و استنباط کا کام آسان ہوگیا۔ یہ کام بھی عثمانی سلطان جودت پاشا کے حکم پر علما کے ایک منظم ادارے ‘مجلہ سوسائٹی’ نےبرسوں کی تحقیق اور مباحث کے بعد انجام دیا۔[48]
عباسی عہد کا بیت الحکمت۔ اسلامی عہد کے تحقیقی اداروں اور فکر گاہوں میں ایک نمایاں نام عباسی عہد کے بیت الحکمت کا ہے۔یہ ادارہ اصلاً عباسی خلفا کے ذاتی کتب خانے کے طور پر قائم ہوا تھا۔ مامون الرشید نے اپنے عہد(سن عیسوی 813-833) میں اسے ایک عظیم الشان علمی و تحقیقی مرکزمیں تبدیل کردیاتھا۔تاتاریوں نے جب (1258 عیسوی میں)بغداد کو تباہ کیا تو اس ادارے کو بھی تاراج کردیا۔[49]
مامون کے بعض خیالات اور دینی رجحانات سے قطع نظر اس کی علم دوستی اور علوم کی سرپرستی کو اسلامی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ مامون نےاس ادارے کے قیام کے بعد باقاعدہ مہم چلاکر ساری دنیاسے ممتاز اہل علم و فن کوجمع کیا ۔[50]دنیا بھر کی اہم علمی کتابیں حاصل کیں اور بغداد میں ترجمہ، اہل علم کے درمیان بحث و گفتگو، تحقیق و ریسرچ، افزائشِ علم اور کتابوں کی اشاعت کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس نے عالمی تمدن پر گہرے دور رس اثرات مرتب کیے۔ محققین جب بھی اسلا م کی علم دوستی اور سائنس اور دریافت و ایجادکی سرپرستی کا ذکر کرتے ہیں تو عملی شہادت کے طورپر بیت الحکمت کا ضرور ذکر کرتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے اُن معاوضوں اور تنخواہوں کاذکرکیا ہے جو بیت الحکمت میں اہل علم کو دی جاتی تھیں۔[51] بعض تنخواہیں آج کی قیمت کے لحاظ سے کئی کروڑ روپیے ماہانہ تک پہنچ جاتی تھیں۔ یونانی ، فارسی، رومی، کلدی، قبطی، شامی، سنسکرت وغیرہ دنیا بھر کی زبانوں کے ماہرین اوردنیا کے ہر ملک سے ممتاز اہل علم جمع کرلیے گئےتھے۔[52]ہندوستان سے بھی کئی ہندو ماہرین اس فکر گاہ کے لیے خاص طور پر طلب کیے گئے تھے اور بھاری تنخواہوں پر مقرر کیے گئے تھے۔ علامہ شبلی نعمانیؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ بیت الحکمت کی کوششوں سےیونان و روم اور دنیا کا «کوئی ایسا علمی خزانہ باقی نہیں رہا جو اہل عرب کی آنکھوں سے چھپا رہ گیا ہو۔[53]ان سب علوم کے ماہرین کے ایک جگہ جمع ہوجانے اور باہم تبادلہ افکار اور بحث و مباحثے کے نتیجے میں یہ ادارہ دنیا بھر کے علوم و فنون اور مختلف شعبہ ہائے علم (disciplines)کے امتزاج کا مرکز (melting pot)بن گیااور بین براعظمی تحقیق (intercontinental research)اور بین تخصصی ریسرچ (interdisciplinary research)کا نیا رجحان اس نے دنیا میں قائم کیا۔
ترجمے کے علاوہ بیت الحکمت نے علوم کی نشوونما اور نئے علوم کی افزائش کا ایک طاقت ور سلسلہ شروع کردیا۔ان علوم پرنظر ڈالنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے تصور کے مطابق انسانوں کی فلاح و بہبود ان علوم کا اصل مقصود تھا۔ ریاضی میں اس ادارے نے عہد ساز کارنامے انجام دیے۔ الخوارزمی نے علم الجبرا کی یہیں بنیاد ڈالی۔[54] ہندوستانی پنڈتوں سے ہندسوں کا علم حاصل کرکےاس ادارے نے اسے نئی بلندیاں عطا کیں اور اعداد کے نظام (Arabic numbers)اور اعشاریہ ( decimal system)کو ساری دنیا میں عام کردیا۔[55]ان کے علاوہ الفرغانی اور البتانی کی فلکیات[56]،حنین ابن اسحٰق کی طب[57]، الکندی کا فلسفہ[58] وغیرہ جیسے دسیوں نافع علوم اس ادارے سے فروغ پائے۔
اس ادارے کا اہم کردار، عباسی خلفا اور ان کے عہدیداروں کو فیصلہ سازی اور پالیسی سازی میں علمی کمک فراہم کرنا بھی رہا، یعنی وہ کردار جسے ہم اس مضمون میں فکر گاہ (think tank)کے عنوان سے زیر بحث لارہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہم فیصلوں اور سرکاری انتظام کی اہم ضرورتوں کے لیے بیت الحکمت کی طرف رجوع کی شاندار روایت مامون نے قائم کی تھی اور اپنے تمام وزرا اور عہدیداروں میں اس روایت کو مقبول بنادیا تھا۔ مامون نے اسی ادارے کی مدد سے کیلنڈر بنوائے [59]اور وقت کے انتظام (time managment)کی نئی پالیسیوں کو عام کیا۔اپنی وسیع سلطنت کے سیاسی، طبعی، موسمی اور طرح طرح کے نقشے تیار کروائے۔[60] عباسی عہدکی مخصوص جنگی حکمت عملی یعنی محاصراتی جنگ(siege warfare)[61] کی اسی ادارے میں صورت گری ہوئی اوریہیں ہائیڈرولک ٹکنالوجی [62](hydraulic technology)پیدا ہوئی جس نے بہت سی ٹکنالوجیوں کی راہ ہم وار کی۔
سلجوقی عہدکامدرسہ نظامیہ بغداد: سلجوقی حکمران الپ ارسلان کے وزیر نظام الملک نے ، 1065 عیسوی میں ،جو اسلامی تاریخ کا بڑا پر آشوب دور تھا(صلیبی جنگیں، بیت المقدس کا سقوط وغیرہ) بغداد کا مدرسہ نظامیہ قائم کیاتھا۔ بہت جلد اس کی شاخیں اصفہان، نیشاپور اور سلجوقی سلطنت کے مختلف مقامات پر قائم ہوگئیں۔[63] بظاہر تو یہ ایک تعلیم گاہ تھی لیکن اسلام اوراسلامی فکرپر چوطرفہ حملوں کے مقابلے کے مقصد سے اس نے ایک اہم علمی و تحقیقی مرکز کی حیثیت سے بھی اپنی پہچان بنائی۔ امام غزالیؒ، ابو اسحاق شیرازیؒ، امام طبریؒ، امام الحرمین الجوینیؒ، ابو بکر بغدادیؒ، ابوبکر ابن عربیؒ، وغیرہ جیسے دسیوںممتاز اسکالراس سے وابستہ رہے۔[64] اس ادارے نے بھی بیت الحکمت کی طرح مختلف علوم وفنون یعنی فلسفہ، منطق، بلاغت، ادب، طب، ریاضی وغیرہ کے ماہرین کو ایک جگہ جمع کیا اور بین تخصصی تحقیق کی راہ ہم وار کی۔[65]اس ادارے نے یونانی منطق و فلسفے کا سحر توڑا۔ معتزلہ،زنادقہ،روافض وغیرہ کے انحرافی افکار کا توڑ کرکے ،اہل سنت کے مسلمہ عقائد وافکار پر عوام اور اہل علم کے اعتماد کو بحال کیا۔وقف کے انتظام، ٹیکس پالیسی، عدالتی اصلاحات، ڈپلومیسی وغیرہ کے سلسلے میں اسلامی افکار کو تحقیق سے آراستہ کرکے پیش کیا۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت، عقیدوں کے انحرافات اور فلسفیانہ و فکری انتہاپسندیوں کا سد باب کیا۔[66] فقہا ، متکلمین اوراہل علم منتظمین (کُتاب ) کی ایک بڑی جماعت تشکیل دے دی اور اسلامی مملکتوں کی پالیسیوں کوٹھوس نظریاتی اساس اور نظریاتی سمت (ideological direction)فراہم کی۔ خود نظام الملک کی تصنیف ‘سیاست نامہ’ (عربی ترجمہ: سیر الملوک)[67] ایک عہدساز کتاب تھی جو عرصے تک مسلمان حکومتوں کی پالیسیوں پراثر انداز ہوتی رہی۔ علامہ شبلی نعمانی ؒکے مطابق اس ادارے کا بجٹ دو لاکھ دینار (موجودہ قیمتوں کے اعتبار سے تقریباًآٹھ ہزار کروڑ روپیے) تھا۔[68]یہ عظیم علمی مرکز بھی ہلاکو خان کی برپا کی ہوئی آندھی میں 1258عیسوی میں تباہ ہوگیا۔
دیگر ادارے:یہ محض چند بڑی مثالیں ہم نے نمونے کے طور پر بیان کی ہیں۔اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسے ادارے کام کرتے رہے ہیں۔فاطمی حکمراں الحاکم بامر اللہ نے عیسوی سن 1005 میں قاہرہ میں دارالعلم قائم کیا ۔ اس ادارے نے ابن الہیثم کی بصریات (optics)اور ابن یونس کی فلکیات جیسے گراں قدر تحفے علمی دنیا کو بخشے۔[69]مراغہ کی رصد گاہ ایرانی ماہر فلکیات نصیر الدین طوسی نے 1259 عیسوی میں قائم کی۔ اس نے ساری دنیا حتی کہ چین تک سے فلکیات اور ریاضی کے ماہرین کو جمع کیا ۔یہیں مشہور ریاضیاتی آلہ جفت طوسی(Tusi Couple)تشکیل پایا۔ ان سب کے اشتراک سے یہاں وہ ریاضیاتی ماڈل تشکیل دیے گئے جن کے نتیجےمیں بطلیموس (ptolemy)کے زمین مرکزیت والے ماڈل کو چیلنج کیا گیا اور کوپرنکس کے سورج مرکزیت والے تصور کی راہ ہموار ہوئی۔[70] شاہ ولی اللہ ؒکے زمانے میں ان کے والد کے قائم کردہ مدرسہ رحیمیہ نے بھی ایک علمی مرکز کی حیثیت اختیار کرلی۔[71]قریبی زمانےمیں حیدرآباد کے دائرة المعارف عثمانیہ[72] اور دارالترجمہ[73] اورعلامہ شبلی کے قائم کردہ دار المصنفین [74]نے بھی گراں قدرخدمات انجام دیں۔
اس تاریخی تجزیے سے اُس غیر معمولی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جواسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں اسلامی تعلیم کی رہنمائی میں چلنے والے تحقیقی اداروں اور فکر گاہوں کو حاصل رہی ہے اور ان کا عملی ماڈل بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے زوال کے ساتھ مسلمانوں کا دیا ہوا یہ شان دار تصور خود مسلمانوں ہی میں ماند پڑتا گیا اور آج نہ صرف علم و تحقیق سے اہل اسلام کا رشتہ بہت کم زور ہوگیا ہے بلکہ تقلید جامد، روایت پرستی، اکابر پرستی ، جذباتیت، سہل پسندی اور بے ساختہ فیصلہ سازی کے ایسے رجحانات ہمارا شعار بن چکے ہیں جو تحقیق و دریافت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ بلکہ ان سے آگے بڑھ کر علم و تحقیق کااستخفاف اور اسے غیر اہم اور غیر ضروری کام سمجھنے کا رجحان بھی پڑھے لکھے لوگوں تک میں خاصا عام ہے۔
اس پس منظر میں اور اس بحث کی روشنی میں موجودہ ہندوستان میں اس محاذ پرکس قسم کی ادارہ جاتی کوششیں مطلوب ہیں، اس موضوع پر ان شاء اللہ اگلےشمارے میں گفتگو ہوگی۔
حواشی و حوالہ جات
[1] الراغب الأصفهانی؛ المفردات فی غریب القرآن؛ دار القلم، الدار الشامیة – دمشق(1992) ؛ص 650
[2] صحیح مسلم ;فی مقدمة الصحیح باب النَّهْىِ عَنِ الْحَدِیثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ، وأبو داود (4992)
[3] سید قطب؛ فی ظلال القرآن (اردو ترجمہ: سید معروف شاہ شیرازی) ادارہ منشورات اسلامی؛ لاہور؛ 1997؛ ج 4ص401
[4] الراغب الأصفهانی؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ص 249
[5] ابن قیم الجوزیة؛مدارج السالكین فی منازل السائرین؛(2019)دار ابن حزم؛بیروت؛ ج3 ص 294
[6] فخر الدین الرازی؛ التفسیر الکبیر؛ دار احیاء التراث العربی؛ 2000؛ ج 4 ص 59
[7] شاہ صاحب کے تفصیلی بیان کا خلاصہ ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:
شاہ ولی اللہ دہلوی؛ البدورالبازغہ؛ (اردو ترجمہ: ڈاکٹر قاضی مجیب الرحمن؛ شاہ ولی اللہ انسٹی ٹیوٹ؛ نئی دہلی؛ ص 269-271
[8] مفردات القرآن،محولہ تدبر قرآن؛ تفسیر البقرہ آیت 129
[9] مولانا سید ابوالاعلی مودودی؛ تفہیم القرآن؛ سورہ البقرہ ؛ آیت 269 (تفہیم القرآن حاشیہ 309)
[10] مولانا ڈاکٹر محمد لقمان سلفی ؛ تفسیر تیسیر الرحمن ؛مکتبہ شاملہ اردو؛ سورہ البقرہ ؛ آیت 269
[11] مولانا سید ابوالاعلی مودودی؛ تفہیم القرآن؛ سورہ المومن؛ آیت 83(تفہیم القرآن حاشیہ 112)
[12] Biomimeticsاب ایک معروف ڈسپلن ہے جس میں مظاہر فطرت اور انفس و آفاق کی آیات پرغورکرکے ٹکنالوجی ڈیولپ کی جاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کے غور وفکر نے کیسی عہد ساز ٹکنالوجیوں کو جنم دیا اس کی چشم کشا تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ایک اہم اسٹڈی
- W. Collins & C. A. Brebbia(Ed.)Design and Nature: Comparing Design in Nature with Science and Engineering (2004) WIT Press;Boston.
[13] سنن ابوداود(1548)؛ سنن ابن ماجہ(250)؛ صححہ الالبانی؛ الصحیح الجامع الصغیر و زیادته (1297)
[14] ابن تیمیہ؛ مجموع الفتاویٰ؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف – المدینة المنورة؛ 2004؛ ج 23 ص 343
[15] ابو اسحٰق الشاطبی، الموافقات؛ دار ابن عفان للنشر والتوزیع ؛ القاهره؛ 1998؛ ج 3 ص89
[16] تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:
Zaiuddin Sardar; Science, Technology and Development in the Muslim World. United Kingdom: Taylor & Francis, 2016.
[17] یوسف القرضاوی؛ الرسول والعلم؛ دارالصحوة؛ القاهره؛ 2001؛ ص 50
[18] جامع ترمذی (2687) سنن ابن ماجہ (4169) یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن درایت اورمفہوم کی بنیادوں پرمتعدد اہل علم نے اسے قبول کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ یوسف القرضاوی؛ الرسول والعلم؛ دارالصحوة؛ القاهره؛ 2001؛ ص 52
[19] شیخ ابو جعفرالطوسی، الامالی ؛1994؛ قسم الدراسات الاسلامیة – مؤسسة البعثة نشر: دار الثقافة – قم ؛3/1290
[20] حوالہ سابق 4/1291
[21] ابن جبیر الطبری؛ تارىخ الرسل والملوك؛ دارالمعارف بمصر(1967) ج 2 ص 566
[22] ابن حجر العسقلانی؛ كتاب الإصابة فی تمییز الصحابة؛ 1995؛ دارالکتب العلمیة؛ بیروت ج1 ص 687؛
[23] بعض روایتوں کے مطابق حارث نے کسی مرحلے مٰیں اسلام قبول کرلیا تھا لیکن اکثر مورخین کے نزدیک وہ ذمی تھے۔ ملاحظہ ہو الاصابہ کا حوالہ مذکور بالا۔
[24] سنن ابو داود؛ کتاب الطب (3875)
[25] سنن ابو داود(4586)، سنن ابن ماجہ(3466)، حسنہ الالبانی (سلسلة الاحادیث الصحیحة 635)
[26] یوسف القرضاوی؛ الرسول والعلم؛ دارالصحوة؛ القاهره؛ 2001؛ ص 48-53
[27] نن الترمذی(1714)؛ باب ما جاء فی المشورة
[28] صحیح البخاری (3132)؛ کتاب فرض الخمس
[29] ابو عبد اللہ القرطبی؛ الجامع لآحکام القرآن؛ دارالکتب المصریۃ؛ القاھرة؛ 1964؛ ج 4 ص 250
[30] الشاه ولی الله الدهلوی ؛ حجة الله البالغة؛ دار الجیل، بیروت؛ 2005؛ ج 1ص 229
[31] ڈاکٹر حمید اللہ، امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی؛ اردو اکیڈمی سندھ؛ کراچی؛ 1965؛ ص 27-28بحوالہ فتح المغیث للسخاوی
[32] مثلاًملاحظہ ہو: ابن حجر ہیتمی؛ الخیرات الحسان؛ دارالہدی والارشاد؛ دمشق؛ 2007 ص 91-100
[33] ڈاکٹر حمید اللہ، امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی؛ اردو اکیڈمی سندھ؛ کراچی؛ 1965؛ ص 40
[34] شیخ محمد ابو زہرہ؛ حیات حضرت امام ابوحنیفہ (ترجمہ اردو: پروفیسر غلام احمد حریری)؛ ملک سنز ؛ فیصل آباد؛ ص 88-100
[35] محمد أمین الشامی(ابن عابدین)؛ رد المحتار على الدر المختار؛ دار الفكر – بیروت ؛1966؛ج1 ص 67
[36] علامہ شبلی نعمانی؛ سیرت النعمان؛ اسلامی کتب خانہ؛ لاہور؛ ص 191
[37] موفق المكی وابن البزاز الكردری؛ مناقب الإمام الأعظم ابی حنیفة؛ دائرة المعارف ؛حیدرآباد؛ 1903؛ص185-186
[38] ڈاکٹر حمید اللہ، امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی؛ اردو اکیڈمی سندھ؛ کراچی؛ 1965؛ ص 52
[39] موفق المكی وابن البزاز الكردری؛ مناقب الإمام الأعظم ابی حنیفة؛ دائرة المعارف ؛حیدرآباد؛ 1903؛ص33
[40] موفق المكی وابن البزاز الكردری؛ مناقب الإمام الأعظم ابی حنیفة؛ دائرة المعارف ؛حیدرآباد؛ 1903؛ج2 ص133
[41] موفق المكی وابن البزاز الكردری؛ مناقب الإمام الأعظم ابی حنیفة؛ دائرة المعارف ؛حیدرآباد؛ 1903؛ج2 ص133
[42] مثلاً ملاحظہ ہو:
محمد ابن أبی العزالصالحی؛ الاتباع؛عالم الكتب – لبنان(1985) ص 40
[43] ڈاکٹر حمیداللہ؛ امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی؛ اردو اکیڈمی سندھ؛ کراچی؛ 1965؛ص52
[44] ابی الموید الخوارزمی؛ جامع مسانید الامام الاعظم ؛ دائرة المعارف؛ حیدرآباد؛ 1914؛ ص33
[45] ڈاکٹر حمید اللہ امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی؛ اردو اکیڈمی سندھ؛ کراچی؛ 1965؛ص49
[46] ڈاکٹر حمید اللہ امام ابوحنیفہ کی تدوین قانون اسلامی؛ اردو اکیڈمی سندھ؛ کراچی؛ 1965؛ص64-67
[47] فتاوی عالمگیری کی تدوین کے اس منصوبے کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ملاحظہ ہو:
مولانا مجیب اللہ ندوی؛ فتاوی عالمگیری اور اس کے مولفین؛ تاج کمپنی، دہلی؛ 1988
[48] محمد فرید؛تاریخ الدولة العلیة العثمانیة؛ دار النفائس؛ بیروت؛2010 ص546-553
[49] تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:
خضر احمد عطا الله ؛بیت الحكمة فى عصر العباسیین؛دار الفكر العربى للطباعة والنشر؛ 1989؛ القاھرہ
[50] Mahmood, A. (2022). Epicenter of Knowledge; A Historic Exploration of Bayt Al Hikmah’s Significance. Journal of Research in Humanities, 58(01), 91–105.
[51] علامہ شبلی نعمانی؛ المامون؛ دارالمصنفین اعظم گڈھ؛ 1992؛ ص168
[52] علامہ شبلی نعمانی؛ المامون؛ دارالمصنفین اعظم گڈھ؛ 1992؛ ص167
[53] علامہ شبلی نعمانی؛ المامون؛ دارالمصنفین اعظم گڈھ؛ 1992؛ ص168-169
[54] تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:
Lim, Bridget., Brezina, Corona. Al-Khwarizmi: Father of Algebra and Trigonometry. United Kingdom: Rosen Publishing, 2016.
[55] Al-Khalili, Jim. The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance. Penguin, 2011, pp. 89–91.
[56] Blake, Stephen P.. Astronomy and Astrology in the Islamic World. United Kingdom: Edinburgh University Press, 2016. Pages 32-33
[57] Prioreschi, Plinio. A History of Medicine: Byzantine and Islamic medicine. United States: Horatius Press, 1996. Pages 207-208
[58] Lim, Bridget., Viegas, Jennifer. Al-Kindi: The Father of Islamic Philosophy. United Kingdom: Rosen Publishing Group, Incorporated, 2016.
[59] ÓKennedy, Edward S. (1956). The House of Wisdom in Baghdad. Isis, 47(1), 4–7. The University of Chicago Press on behalf of the History of Science Society.
[60] Lyons, Jonathan. The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization. United Kingdom: Bloomsbury Publishing, 2010.page 90
[61] Whitney, Elspeth. Medieval Science and Technology. United Kingdom: Bloomsbury Publishing, 2004. page 124
[62] https://muslimheritage.com/hydraulic-organ-of-banu-musa/; retrieved on 8-4-2025
[63] علامہ شبلی نعمانی؛ مقالات شبلی؛ حصہ سوم؛ دارالمصنفین اعظم گڈھ؛ 2009؛ ص44-47
[64] درج ذیل مصادر سے یہ نام لیے گئے ہیں:
علامہ شبلی نعمانی؛ مقالات شبلی؛ حصہ سوم؛ دارالمصنفین اعظم گڈھ؛ 2009؛ص46
ابن الدبیثی؛ تاریخ مدینة السلام ;دار الغرب الإسلامی ;2006 – جزء 2 – صفحة 268
[65] تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:
ڈاکٹر سہیل شفیق؛ جامعہ نظامیہ بغداد کا علمی و فکری کردار؛ عکس پبلی کیشنز؛ لاہور
[66] ڈاکٹر سہیل شفیق؛ جامعہ نظامیہ بغداد کا علمی و فکری کردار؛ عکس پبلی کیشنز؛ لاہور ص 120-160
[67] نظام الملوک الطوسی؛ سیر الملوك؛ دار الثقافة – قطر؛ 1987
[68] علامہ شبلی نعمانی؛ مقالات شبلی؛ حصہ سوم؛ دارالمصنفین اعظم گڈھ؛ 2009؛ ص47
[69] Verde, Tom (2019) Cairo’s House of Knowledge. Aramco World.(Jan/Feb).available at: /https://www.aramcoworld.com/-/media/aramco-world/issues/files/2019/january-february-2019.pdf retrieved on 6/04/2025
[70] Stephen P. Blake; Astronomy and Astrology in the Islamic World; 2016; Edinburgh University Presspp. 73 – 87
[71] مولانا امداد صابری؛ دہلی کے قدیم مدارس اور مدرس؛ صابری اکیڈمی؛ نئی دہلی؛ 1977 ص 113-120
[72] محمد یوسف سورتی؛ دائرة المعارف النظامیہ اور کتب قدیمہ کی اشاعت؛ ماہنامہ معارف؛ اعظم گڈھ؛ جنوری اور فروری 1932;
[73] ڈاکٹر مجیب الاسلام؛ دارالترجمہ عثمانیہ کی علمی وادبی خدمات؛1987انجمن ترقی اردو؛ دہلی
[74] پروفیسر خورشید نعمانی؛ دارالمصنفین کی تاریخ اور علمی خدمات؛ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی؛ 2004؛ اعظم گڈھ