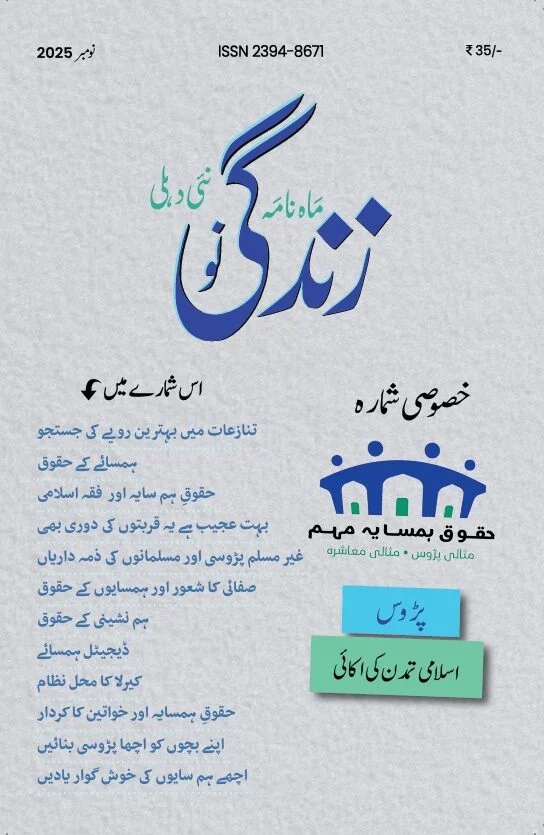اول روز سے ہی اسلام کا پیغام آفاقی اور اس کی دعوت عالمی ہے۔ مدینہ منورہ جیسے ہی کثیر الاقوام اور کثیر الادیان نبوی ریاست کا دارالحکومت قرار پایا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق مدینہ‘‘مسلمانوں، مشرکوں، بت پرستوں اور یہودیوں ’’ کا ملا جلا سماج بن گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےامام ابو الولید الباجی (م: 484ھ/1018ء) کی تعبیر کے مطابق ’دینی و دنیوی سربراہی میں یکتا امامِ امت‘ کی حیثیت سے ’’دستور مدینہ ’’ کا اعلان فرمایا۔ یہ وہ دستور تھا جس نے بقائے باہم اور مل جل کر زندگی گزارنے کی بنیادیں وضع کیں۔ ان بنیادوں نے مدینے کو یا اسلامی ریاست کو ’’دیگر لوگوں کے مقابلے میں ایک امت‘‘ کی حیثیت دے دی تھی، اور یہ حیثیت انھیں مذہب یا نسل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ شہریت کے اصول پر حاصل ہوئی تھی۔
اس نئے ’’وطن‘‘ کے اجزائے ترکیبی میں رواداری کے ساتھ مل جل کر رہنے کی جو بنیادیں رسول اللہ ﷺ نے وضع فرمائی تھیں وہ قرآن کریم کی درج ذیل توجیہات و ارشادات پر عمل آوری تھی:
لَا إِكْرَاهَ فِی الدِّینِ (سورة البقرة،آیت: 256)
’’دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔‘‘
لَا ینْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوكُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیارِكُمْ أنْ تَبَرُّوهُمْ (سورة المُمْتَحَنَة، آیت: 8).
’’اللہ تمھیں ان لوگوں سے نہیں روکتا ہے جنھوں نے دین کے معاملے میں نہ تو تم سے قتال کیا ہے اور نہ تمھیں تمھارے گھروں سے نکالا ہے، کہ تم ان کے ساتھی نیکی کا معاملہ کرو۔‘‘
اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کے رسولﷺ نے عیسائی مہمانوں کو مسجد نبوی کے اندر ان کے مذہبی شعائر کی ادائیگی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ امام ابن القیم (م: 751ھ/ 1350ء) نے اپنی کتاب ’’احکام اہل الذمۃ‘‘ میں ذکر کیا ہے کہ نبیﷺ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آپؐ نے 9 ہجری /631 عیسوی میں نجرانی عیسائیوں کے 14 افراد پر مشتمل ایک وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ اس دوران ان کی عبادت کا وقت ہو گیا تو انھوں نے مسجد میں ہی عبادت کی۔‘‘ امام ابن القیم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس روایت سے بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں اہل کتاب کا داخلہ جائز ہے۔‘‘
نبیﷺ نے صحابہ کرام ؓکو طریقہ سکھایا کہ ’’اہل کتاب‘‘ ان کے ساتھ کوئی نیکی کریں تو انھیں کس طرح دعا دی جائے۔ امام ذہبی (م: 749ھ/1348ء) نے ’’تاریخ الاسلام‘‘ میں عبداللہ بن عمر بن خطابؓ (م: 73ھ/693ء) کی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ نبیﷺ نے فرمایا:
’’تم لوگ یہود اور نصاری میں سے کسی کے لیے دعا کرو تو یوں دعا کرو: ’’اللہ تمھارے مال اور اولاد میں بڑھوتری کرے۔‘‘
تاریخ کے ان تمام ادوار میں جب کہ امت اسلامیہ اپنی فکری صحت مندی اور ثقافتی آسودگی سے لطف اندوز رہی، صحابہ کرام، ان کے بعد تابعین اور ان کے بعد تمام انصاف پسند مسلمان اسی نبوی نقشِ قدم پر گام زن رہے۔ اسلامی فتوحات حاصل کرنے والے اسلامی کمانڈر مفتوحہ علاقوں کے رہنے والوں کو ’’جان، مال، مذہبی شناخت، چرچ اور صلیبوں‘‘ کی امان فراہم کیا کرتے تھے۔ ان کے ان حقوق میں کچھ بھی کمی نہیں کی جاتی تھی اورنہ ان کے ساتھ ان کے اہل مذہب کے علاوہ کوئی دوسرا سکونت اختیار کر تا تھا۔ تاریخ میں ’’عیسائی قاضی (جسٹس) اور ’’یہودی قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کابھی ذکر ملتا ہے، جسے اصطلاح میں ’’ناجد‘‘ کہا جاتا تھا۔
امام ابن کثیرؒ (م: 774ھ/1373ء) ’البدایہ و النہایہ‘ میں بیان کرتے ہیں کہ دمشق کے اندر مسلمان اور عیسائی ستر برس تک ایک ہی عبادت گاہ میں اپنی اپنی عبادت کیا کرتےتھے۔ اس عبادت گاہ کا نصف حصہ چرچ پر مشتمل تھا اور دوسرا نصف حصہ مسجد تھا۔ ’’مسلمان اور عیسائی دونوں ایک ہی دروازے سے عبادت گاہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ اندر داخل ہو کر عیسائی مغربی جانب چلے جاتے تھے، جس طرح چرچ تھا اور مسلمان دائیں جانب اپنی مسجد کی طرف مڑ جاتے تھے۔‘‘
یہ وہی عبادت گاہ ہے جو 86ھ/705ء میں فریقین (مسلمان اور عیسائیوں)کی رضامندی کے بعد خالص مسلمانوں کی مسجد قرار پائی اور تاریخ میں آج تک اسے ’’الجامع الاموی‘‘ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد اسلام کا ایک تعمیراتی نمونہ شمار کی جاتی ہے۔ مزید بر آں یہ مسجد رواداری پر مبنی بقائے باہم کا نمایاں ثبوت ہے۔
مصر کے تعلق سے فقیہ و مورخ المقریزی (م: 845ھ/1441ء)‘المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار‘‘ میں سرزمین اسلام پر اہل مذاہب کے درمیان تعلقات کی ایک روشن تصویر پیش کرتےہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ’’ امیر مصر علی بن سلیمان ابن عباس (م: 178ھ/ 794ء) نے مریم چرچ اور محرس قسطنطین کے چرچوں کو منہدم کر دیا۔۔۔۔ پھر جب موسی بن عیسی ابن عباس (م 183ھ/799ء) کو معزول کیا گیا تو عیسائیوں کو علی بن سلیمان کے ذریعے منہدم کیے جانے والے چرچ کودوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی۔ چناں چہ امام لیث بن سعد (م: 175ھ/791ء) اور امام عبداللہ بن لہیعہ (م: 174ھ/790ء) کے مشورے سے تمام منہدم شدہ چرچوں کو تعمیر کرایا گیا۔ ان دونوں ائمہ نے یہ بھی کہا کہ یہ چرچ ملکی عمارتیں ہیں۔ اس کی دلیل انھوں نے یہ دی کہ مصر میں جتنے بھی چرچ ہیں وہ زمانہ اسلام میں صحابہ و تابعین کے عہد میں تعمیر ہوئے ہیں۔‘‘‘‘ملکی عمارت‘‘ کی جو تعبیر دونوں اماموں کی گفتگو میں مذکور ہوئی ہے وہ اس بلند خیال کا خلاصہ پیش کرتی ہے جو مذہبی تکثیریت، رواداری، آزادی مذہب اور عبادت گاہوں کی تعمیر بلکہ ان کے تحفظ کے سلسلے میں اسلامی تہذیب کا امتیاز رہا ہے۔ اسلام کا یہ وژن ہمارے موجودہ دور کے معیار سے بھی بہت آگے کا ہےجسے بین الاقوامی اصولوں اور بین الاقوامی معاہدوں کی روشنی میں ڈھالا گیا ہے۔
دوسری صدی ہجری، یعنی آٹھویں صدی عیسوی کے اواخر سے مسلمانوں کے اندر اقدار کا زوال شروع ہوا تو عدل و اخلاق کے بہت سے پیمانے متاثر ہوگئے۔ سیاسی فتنوں اور سماجی بحرانوں کی زد میں سماجی ظلم و زیادتی عام ہو گئی اور معاشرے کا داخلی تانا بانا ادھڑنے لگا۔
اس کے بعد چوتھی صدی ہجری/ دسویں صدی عیسوی میں غیر ملکی عوامل و اسباب نے اس صورت حال کو مزید گہرا کر دیا۔ یہ غیر ملکی عوامل و اسباب اسلام پر چاروں طرف سے بیرونی خطروں کی شکل میں سامنے آئے تھے، جن کی وجہ شام میں دیار اسلام پر بازنطینی حملے، مشرق اسلامی پر صلیبی فرنگیوں کے حملے اور اندلس میں مسلمانوں کے خلاف اسپینی مسیحیوں کی جنگ بنی تھی۔
اکثر اس صورت حال کو ان خطرات اور اسلامی علاقوں میں موجود ان غیر مسلموں سے مربوط کر کے دیکھا جاتا ہے جن سے اسلامی علاقوں کو نقصان پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی علاقوں کی عام آبادی پر مشتمل غیر مسلموں نے بیش تر حالات میں ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھا جس کی وجہ سے اسلامی علاقوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حتی کہ امریکی مورخ ’ول ڈیورینٹ (م: 1402ھ/ 1981ء) اپنی کتاب ’’اسٹوری آف سویلائزیشن‘‘ میں صلیبی جنگوں کے اہم ترین نتائج کے ضمن میں لکھتا ہے کہ اسلامی حکومتیں جو کبھی اہل مذاہب کے ساتھ رواداری کے سلسلے میں ممتاز تھیں، اسلامی ملکو ں پر لگاتار صلیبی اور یوروپی حملوں کی وجہ سے یہ رواداری ختم ہو چکی تھی‘‘
علوم و معارف کا لین دین
مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ایجابی بقائے باہم کا اولین مظہر شاید یہی ہے کہ ان کے درمیان علوم و معارف کا تبادلہ ہوا کرتا تھا اور یہ سلسلہ تاریخ اسلامی کے پورے دور میں جاری رہا۔ چناں چہ اسلام کے اولین عہد میں بہت سےمسلمانوں نے یہودی اور عیسائی علما سے مختلف ایسے علوم حاصل کیے جو اسلامی تعلیمات وحقائق سے ٹکراتے نہیں تھے۔ اس کی ایک مثال حافظ ابن کثیر عسقلانی (م: 852ھ/1448ء) نے ’’تہذیب التہذیب‘‘ میں بیان کی ہے کہ مفسر امام مقاتل بن سلیمان البلخی (م: 150ھ/768ء) ’’یہود و نصاری سے قرآنی علوم کے سلسلے میں ان کی مقدس کتابوں کا وہ علم حاصل کیا کرتے تھے جو قرآن سے مطابقت رکھتاتھا۔‘‘ اگرچہ مقاتل کے سلسلے میں جو آراء پیش کی گئی ہیں وہ جرح و تعدیل سے تعلق رکھتی ہیں، تاہم مسلمانوں میں رائج قابل اعتماد تفسیروں میں سے ایک بھی تفسیر ایسی نہیں ہے جس میں ان کی رائے مذکور نہ ہو۔
اسی طرح امام مغازی محمد بن اسحاق (م: 151ھ/769ء) یہود و نصاری سے علم لیتے ہیں اورجیسا کہ ابن ندیم نے اپنی کتاب ’الفہرست‘ میں ذکر کیا ہے، ابن اسحاق اپنی کتابوں میں انھیں ’’اولین اہل علم‘‘ کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ امام طبری (م: 310ھ/922ء) اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 235ھ/ 849ء میں عباسی خلیفہ متوکل (م: 247ھ/ 861ء) نے غیر مسلموں کے تعلق سے امتیازی فیصلے صادر کیے۔ ان فیصلوں کی رو سے اس نے ممنوع قرار دیا تھا کہ غیر مسلمین مسلمانوں کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کریں اور مسلمان ٹیچر انھیں تعلیم دیں۔‘‘ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کی تعلیم گاہوں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔
ابن خلکان(م: 681ھ/1282ء) ’’وفیات الاعیان‘‘ میں بیان کرتے ہیں کہ معروف مسیحی طبیب یحیی بن جزلہ (م: 493ھ/1100ء) علی ابو علی ابن الولید معتزلی (م: 478ھ/1085ء) سے درس لیا کرتا تھا اور اپنا پورا وقت اسی کےساتھ گزارتا تھا۔ اور ابو محمد الغَنَوی شافعی (م: 660ھ/1262ء) اپنے مکان (واقع دمشق) میں عزلت نشین رہتے تھے۔۔ مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور سامریوں کی جماعتوں کی ان کے یہاں آمدورفت رہا کرتی تھی۔ ابن تغری بردی (م: 874ھ/1470ء) کے مطابق وہ انھیں کتاب ’’النجوم الزاہرہ‘‘ پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا واقعہ امام سیوطی (م: 911ھ/1506ء) نے ’’بُغیۃ الوُعاۃ‘‘ میں شمس الدین محمد بن یوسف الجزری شافعی (م: 711ھ/1311ء) سے نقل کیا ہے کہ ’’وہ پڑھانے کے لیے جوکس ہو کر بیٹھ گئے تو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کےسامنے سبق پڑھا۔ وہ قاہرہ کی جامع طولونی کے خطیب بھی تھے۔ التقی السبکی (م: 756ھ/1355ء) نے بھی ان سے سبق پڑھا اور ان سے روایت نقل کی ہے۔‘‘
ابن حجر کی ’’الدرر الکامنۃ‘‘ میں عبد السید بن اسحاق اسرائیلی (م: 715ھ/1315ء) کے حالات زندگی کے ضمن میں یہ مذکور ہے کہ ابن اسحاق اسرائیلی یہودیوں کے لیے مذہبی مرجع کے حیثیت رکھتے تھے۔ وہ مسلمانوں سے محبت رکھتے تھے۔ حدیث کی مجلسوں میں شریک ہوا کرتے تھے اور شام کے محدث حافظ المزّی (م: 742ھ/1341ء)نے انھیں حدیث بھی سنائی۔ بعد میں اللہ نے انھیں ہدایت دی اور وہ اسلام لے آئے۔‘‘ سماعت حدیث کی مجالس میں حاضری کے علاوہ بعض عیسائی اور یہودی مسلمان صوفیا کی مجالس سماع میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے امام ذہبی نے ’’تاریخ الاسلام‘‘ میں لکھا ہے کہ سلسلہ حریریہ کی بنیاد رکھنے والے شیخ ابوالحسن الحریری (م: 645ھ/1262ء) نے ’’اپنے شاگردوں کو سماع کے وقت دروازہ بند کرنے سے منع کر دیا تھا حتی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا تھا۔‘‘
اجتماعی بحران
تاریخ اسلام میں بار بار پیش آنے والا ایک منظرنامہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں افسران و حکام کے ظلم و تشدد کے خلاف اجتجاجی مظاہرے ہوا کرتے۔ عام طور پر ظلم و زیادتی کے خلا ف تشکیل دیے جانے والے قومی محاذ میں تمام مذہبی گروہ شریک ہوا کرتے۔ اس سلسلے کا ایک عجیب و غریب واقعہ دمشق میں پیش آیا۔ اس احتجاجی مظاہرے میں ہر مذہبی گروہ نے اپنی مقدس مذہبی کتاب اٹھا رکھی تھی اور الجامع الاموی کے اندر سب لوگوں نے مل کر دعائیں مانگیں۔
المقریزی (م: 845ھ/1441ء) نے ’’اتّعاظ الحنفا‘‘ میں ذکر کیا ہے کہ 363ھ/947ء میں مصر کا فاطمی سپہ سالار ابو محمود ابراہیم بن جعفر البریری الکتامی (م: 370ھ/981ء) دمشق میں داخل ہوا۔ اس وقت دمشق کا امن و استحکام برباد ہو چکا تھا۔ حالات جب بہت ابتر ہو گئے تو اہل دمشق نے شہر کے مشائخ کی قیادت میں مظاہرے کیے جن میں بدامنی کی مذمت کی گئی اور امن کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں ’’مسلمانوں نے قرآن، عیسائیوں نے انجیل اور یہودیوں نے تورات کھول کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ الجامع الاموی میں یہ سب لوگ اکٹھا ہوئے اور بلند آواز سے دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد پورے شہر کا چکر اس طرح لگایا کہ ان کی مذہبی کتابیں ان کے سرو ں پر کھلی ہوئی رکھی تھیں۔‘‘
عراق میں بویہی وزیرابوالفضل شیرازی (م: 362ھ/973ء) کے ظلم نے شدت اختیار کی تو بغداد کی جامع مسجدوں، چرچوں اور یہودی معبدوں میں اس کے خلاف کثرت سے دعائیں مانگی جانے لگیں۔ فاطمی خلیفہ حاکم بامر اللہ (م: 411ھ/973ء) کا اپنی رعایا پر ظلم حد سے گزرا تو اس کےکتامی حلیف اکٹھا ہوئے اور انھوں نے خلیفہ سے گہار لگائی۔ اسی طرح تمام کلرکوں، مزدوروں، سپاہیوں اور تاجروں— عیسائیوں اور یہودیوں نے اس سے معافی کی درخواست کی۔ ’’ مقریزی مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے معانی نامے کی ایک نقل مسلمانوں کے نام، ایک نقل عیسائیوں کے نام اور ایک نقل یہودیوں کے نام جاری کی۔
394ھ/1005ء میں فاطمی حکومت کے بڑے عیسائی عہدے دار نے شام کے مسلم و غیر مسلم باشندوں سے ظلم کو رفع کرنے کے لیے مداخلت کی۔ اس سلسلے میں اس نے فاطمی خلیفہ فاطمی خلیفہ حاکم بامراللہ کی بہن ’ستّ الملک (م: 415ھ/1025ء) سے اپنے تعلقات کا سہارا لیا۔ یہ خاتون اس عیسائی عہدے دار کا لازمی طور پر لحاظ کیا کرتی تھی۔چناں چہ مسیحی عہدے دار نے اس کے نام خط لکھ کر اس سے فریاد کی اور تمام اہل شام پر ظلم و جور کی جو مصیبت آئی ہوئی تھی اس کی شکایت کی۔ اس کی شکایت پر ستّ الملک ظلم کے ازالے کے سلسلے میں حاکم بامراللہ کے دربار میں داخل ہوئی اور حاکم نے اس کی سفارش قبول کر لی۔ ابن القلانسی تمیمی (تاریخ دمشق) کےمطابق حاکم بامراللہ مختلف امور میں اپنی بہن سے مشورہ کیا کرتا اور اس کی رائے پر عمل کرتا تھا۔
ایک دوسرے سے ہم دردی
غم اور جنگ کے مواقع پر مختلف مذہبی طبقات کے درمیان اتحاد و ہمدردی کی صورت میں یگانگت اور ہم آہنگی کی جوجھلک بکثرت نظر آتی ہے وہ اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ کسی بھی مذہبی طبقے کی سرکردہ شخصیت کا جنازہ ہو، جنگی حالات کے دوران لڑائی کا موقع ہو، کسی کو پناہ دینے یا مدد فراہم کرنے کی ضرورت ہو تو ہر طبقہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔ اس کی قدیم ترین شہادت جو کہ عجیب و غریب بھی ہے، وہ ہے جو امام بخاری (م: 256ھ/780ء) کی ’’التاریخ الاوسط‘‘ میں اور محدث ابن ابی شیبہ(297ھ/910ء) کی کتاب ’’المصنّف‘‘ میں امام شعبی(106ھ/725ء)کی روایت سے نقل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا جو کہ عیسائی تھی۔ اصحاب محمدﷺ نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔
حافظ ابن عساکر(م: 571ھ/1175ء) نے تاریخِ دمشق میں ذکر کیا ہے کہ مذکور بالا عیسائی خاتون کا نام ’سبحاء حبشیہ‘ تھا۔ قرائن اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا انتقال اس کے صحابی شوہر عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی کی وفات (35ھ/656ء) کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ مشہور شاعر عمر بن ابی ربیعہ (م: 93ھ/713ء) کے والد تھے۔
اسی طرح ابوحنیفہ دینوری کی کتاب ’الاخبار الطوال‘ میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ 40ھ/661ء کے ماہ رمضان میں کوفہ کی گلیوں سے ایک جنازے کوگزارا گیا جس کے ساتھ اشراف عرب (مسلمان) بھی چل رہے تھےاور عیسائی پادری بھی چل رہے تھے۔ عیسائی پادری انجیل کی قراءت کرتے جا رہے تھے۔ لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: ابحر بن جابر العِجلی کا ہے۔ یہ شخص عیسائیت کی حالت میں مرا تھا۔ اور اس کا بیٹا حجار بن ابحر بکر ابن وائل کا سردار تھا۔ مسلمان اشراف نے جنازے میں اس لیے شرکت کی تھی کہ اس کا بیٹا سردار تھا اور عیسائی اس سے اپنی مذہبی نسبت کے سبب شریک ہوئے تھے۔
امام ابن شیبہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ جلیل القدر صحابی حضرت ابن عمرؓ (م: 73ھ/693ء) سے مسلمان فرد کے متعلق سوال کیا گیا کہ کوئی عیسائی خاتون مر جائے تو وہ اس کے جنازے میں شرکت کرے یا نہ کرے؟ انھوں نے جواب دیا: جنازے میں شریک ہو اور اس کے آگے چلے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور حدیث میں یہ اشارہ گزر چکا ہے کہ ’’نبیﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ کسی نے عرض کیاکہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے! آپؐ نے فرمایا: ’’کیا وہ انسان نہیں ہے؟‘‘
دوسری طرف امام و زاہد منصور بن زاذان الواسطی کا 128ھ/747ء میں انتقال ہو گیا۔ یہودی، عیسائی اور مجوسی روتے ہوئے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اسی طرح حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ یہود، نصاری اور قبطی امام اوزاعی کے جنازےکے ساتھ چل رہے تھے۔
ابن عساکر ہی نے ’صاحبِ سِتر‘ امام فزاری (م: 186ھ/803ء) کے متعلق لکھا ہے کہ ’’جب ابو اسحاق الفزاری کا انتقال ہوا تو میں نے یہودیوں اور نصرانیوں کو دیکھا کہ ان کے انتقال کے غم میں اپنے سروں پر مٹی ڈال رہے ہیں۔‘‘ امام الفزاری کا شمار ’’ائمہ مسلمین اور اعلام دین‘‘ میں ہوتا تھا۔ خطیب بغدادی (م: 463ھ/1071ء) نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ جس دن امام احمد بن حنبل(م: 241ھ/855ء) کا انتقال ہوا مسلمان، یہودی، نصاری اور مجوسی چاروں ہی گروہوںمیں ماتم اور نوحے کی صفیں بچھ گئیں۔ ’’
امام ذہبی نے اندلسی مورخ ابن بشکوال کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مغرب اسلامی میں اندلس کے بڑے عالم عبداللہ بن یحیٰ بن یحیٰ اللیثی قرطبی (م: 298ھ/912ء) کا انتقال ہوا تو‘‘دیکھا گیا کہ ان کی وفات پر رونے والوں میں ہر طبقے کے لوگ، حتی کہ یہودی اور عیسائی بھی شامل تھے۔‘‘
ابن عساکر کی ہی کتاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ فارس میں اپنے وقت کے شیخ صوفی محمد بن خفیف الضبی شیرازی کا 371ھ/982ء میں انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں ’’یہودی، عیسائی اور مجوسی ایک ساتھ جمع تھے۔‘‘ امام ذہبی تو کہتے ہیں کہ جب عالم و زاہد امام ابن ابو نصر ملقب بہ ’’عفیف‘‘ کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ سب سے آگے علمائے حدیث تھے جو تہلیل وتکبیر کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ شہر کے تمام باشندے حتی کہ یہودی اور عیسائی بھی جنازے موجود تھے۔
جنگوں میں مشترکہ شرکت
ہنگامی حالات اور جنگ کے میدان میں متعدد بار ایسا ہوا کہ عیسائیوں نے بعض مسلم سلاطین کے تابع فوجوں میں شرکت کی۔ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگوں میں حصہ لیا۔ اس کے اثبات میں بطور نمونہ وہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے جس کا ذکرہمیں مورخ ابن العبری (م: 685ھ/1286ء) کی ’تاریخ مختصر الدول‘ میں ملتا ہے کہ سلجوقی سلطان غیاث الدین (م: 644ھ/1246ء) کو بابا ترکمانی(م: 638ھ/1240ء) کی تحریک بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔اس شخص نے نبوت کا دعوی کر دیا تھا اور اپنی دعوت کو عام کرنے کے لیے چھے ہزار شہ سوار جمع کر لیے تھے۔ سلطان غیاث الدین نے اس کے خلاف جنگ کے لیے ایک فوج روانہ کی جس میں سلطان کے فرنگی ملازموں کی ایک ٹکڑی بھی شامل تھی۔ انھوں نے بھی بابا ترکمانی کی فوج کے خلاف جنگ لڑی۔ مسلمان فوج کو بابا ترکمانی کی فوج کے خلاف جنگ کی جرأت نہیں ہوئی اور اس کی قوت کا غلط اندازہ لگا کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت انھی فرنگیوں نے مسلمانوں کو پیچھے کرکے خوارج کے خلاف جنگ کا مورچہ سنبھالا اور اس طرح خوارج کو نشانہ بنایا، ان کے خلاف تلوار زنی کی اوربے دردی سے انھیں قتل کر ڈالا۔ ان مقتولین میں بغاوت کا سرغنہ بھی تھا۔
آئیے اس کا موازنہ اس واقعے سے کریں جو اس حادثےکے پانچ برس بعد 642ط/1244ء میں اس وقت پیش آیا تھا جب کہ دمشق اورحمص کے بادشاہوں اور کرک ایوبیوں نے اپنے ہی مسلمان بھائی اور چچا زاد سلطان مصر نجم الدین ایوب (م: 648ھ/1249ء)کے خلاف صلیبیوں کو اپنا حلیف بنالیا تھا۔ یہ تمام لوگ فرنگی جھنڈوں تلے سروں پر صلیبیں لیے آگے بڑھ رہے تھے۔
جیسا کہ امام موفق الدین ابن قدامہ حنبلی (م: 620ھ/1223ء) اپنی کتاب ’’الکافی‘‘ میں لکھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات نے غیر مسلم شہریوں کی حفاظت اور مسلمان ہوں یا کفار، انھیں نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ان کا دفاع، اور کوئی قیدی بنا لیا جائے تو اس کی رہائی کو واجب ولازم قرار دیا ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے تحفظ کو جہاد کے شرعی مقاصد میں شمار کیا ہے۔ (سورة الحج/الآیة: 40)
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عملی طور پر کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ مسلمان جو فکری ونظریاتی طور پر مسلم سلطنت کے مخالف تھے انھیں بطور سزا دشمن کی قید میں چھوڑ دیا گیا، جب کہ دوسری طرف غیر مسلموں کو حفاظت فراہم کی گئی اور ذِمّی قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کرا لیا گیا۔ چناں چہ طبری نے اپنی کتاب (تاریخ الطبری) میں 231ھ کے واقعات و حوادث کے ضمن میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ قسطنطنیہ میں رومیوں کی قید میں جو مسلمان تھے انھیں فدیہ دے کر چھڑایا گیا۔ عباسی خلیفہ الواثق باللہ (م: 232ھ/848ء) نےرہائی کرانے والے وفد میں ایک شخص ایسا بھی بھیجا جو مسئلہ خلقِ قرآن کے سلسلے میں مسلمان قیدیوں کا امتحان لے۔ ’’جس نے خلقِ قرآن کی حمایت کی اسے رومیوں کی ہی قید میں چھوڑ دیا گیا۔‘‘
عماد اصفہانی (م: 597ھ/1200ء) ’’البستان الجامع‘‘ میں بیان کرتے ہیں کہ جس وقت صلیبی فرنگیوں نے (541ھ/1246ء میں) شہر ’الرُّہا‘ ( موجودہ ترکی شہر ’اورفا‘) اور اس کے قریبی قلعے پر غلبہ حاصل کر لیا تو ’شہر کے یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کوقیدی بنا لیا۔۔۔۔، چناں چہ مسلمانوں کی افواج نے یکجا ہو کر فرنگیوں کے خلاف حملہ کیا۔۔۔ اور تمام قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔‘‘ جس طرح صلیبی قابضوں نے اپنے قبضے اور ظلم کے دوران اہلِ مذاہب کے درمیان کوئی تفریق نہیں، اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان کی حمایت و دفاع اور قید سے آزادی دلانے میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی۔
اس ضمن میں انتہائی اہمیت کا حامل واقعہ امام ابن تیمیہ (م: 728ھ1328ء) کا ہے جو ان یہودی اور عیسائی قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہے جنھیں تاتاریوں نے 699ھ/1300ء میں دمشق پر حملے کے دوران قیدی بنا لیا تھا۔ امام ابن تیمیہ نے قبرص کے مسیحی بادشاہ سرجون کو ایک خط لکھا، جس میں انھوں نے یہ بھی لکھا کہ ’’تمام نصاری یہ بات جان چکے ہیں کہ میں نے۔۔۔۔ قیدیوں کی رہائی کے سلسلے میں تاتاریوں سے بات کی ہے۔۔۔۔ چناں چہ ان کے بادشاہ غازان (م: 703ھ/1303ء) نے مسلمانوں کی رہائی کی اجازت دے دی، اور مجھ سے کہا کہ ’لیکن ہمارے پاس کچھ عیسائی ہیں جنھیں ہم نے القدس سے اپنے ساتھ لیا ہے۔ وہ لوگ رہا نہیں کیے جائیں گے۔‘ میں نے کہا: نہیں، بلکہ ہمارے جو بھی ذمی یہودی اور عیسائی آپ کے پاس ہیں آپ ان سب کو رہا کریں گے۔ ہم نہ انھیں چھوڑیں گے اور نہ کسی دوسرے قیدی کو چھوڑیں گے خواہ وہ امت مسلمہ کا فرد ہو یا ذمیوں میں سے ہو۔ ہم نے عیسائیوں میں جس کو اللہ نے چاہا رہا کر دیا۔ یہ ہے ہمارا عمل اور حسن سلوک اور اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔‘‘ (جاری) (ماخذ: الجزیرہ عربی ویب سائٹ)