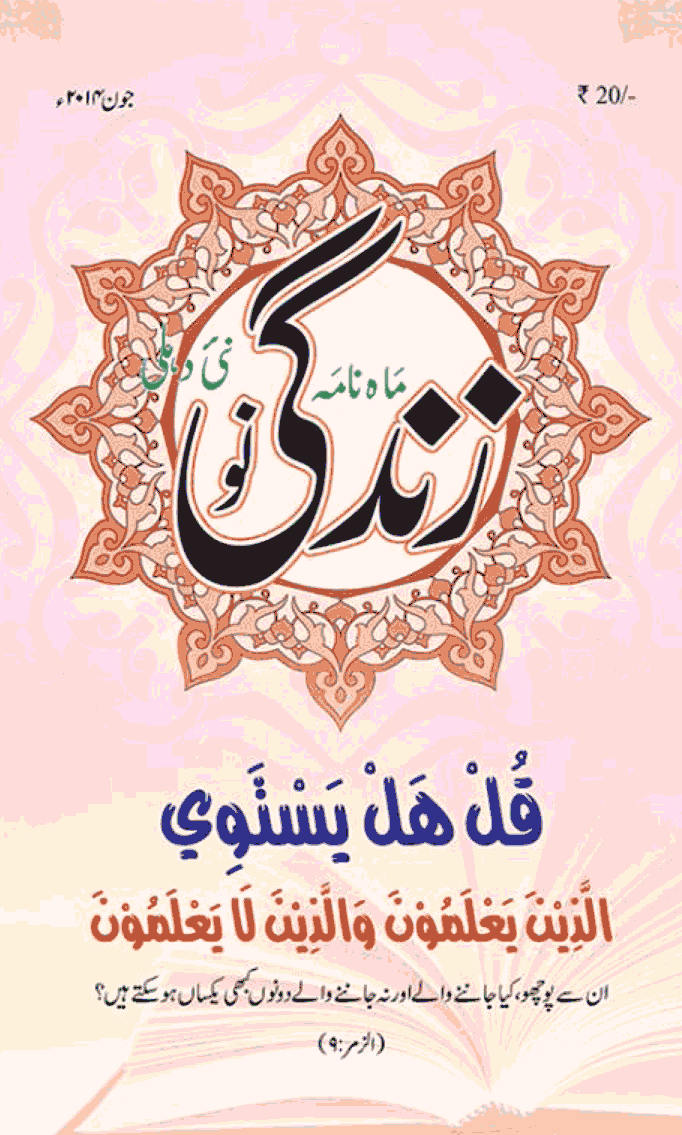کوئی پڑھا لکھا آدمی یہ نہ جانے کہ مصر کسی ملک کا نام ہے یا چڑیا کا، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات تب ہوگی جب وہ کہے کہ وہ اہرامِ مصر کو نہیں جانتا۔ اہرام مصر۔۔۔ نئی اور پرانی، دونوں دنیا کے سات عجوبوں میں سے ہے۔ اہرامِ مصر۔۔۔ جس کی تعمیر آج سائنس کی بے مثال ترقیوں کے باوجود ایک معمہ ہے۔ ویسے تو آج تک مصر میں کل ۱۳۸ اہرام دریافت کئے جاچکے ہیں لیکن الجیزہ کے اہرام اپنی جسامت، حسن اور رعب و دبدبے کے اعتبار سے ایک نرالی شان رکھتے ہیں۔ اہرامِ مصر کی ایک بڑی سی تصویر دیکھ کر اچانک میرے ذہن میں یہ خیال بلکہ سوال آیا کہ کیا الجیزہ میں واقع وہ تین بڑے اور تین چھوٹے اہرام دنیا کے ہر سیاح کو ایک جیسے نظر آتے ہیں؟ سوال بیوقوفانہ ہے لیکن یہ سوچ کر ہمت بندھی کہ دنیا کی تاریخ میں ہر اس فلسفی کا عقیدت و احترام سے ذکر کیا جاتا ہے جس نے ایسے ہی ’بیوقوفانہ‘ سوالات پر سر کھپایا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے سوال پر ہر پہلو سے غور کرنا شروع کیا۔ غوروفکر کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ جب ایک تختۂ سیاہ، قلم اور کتاب مجھے بھی اور دنیا کے ہر انسان کو تختۂ سیاہ، قلم اور کتاب ہی نظر آتے ہیں تو اہرامِ مصر ہر سیاح کو ایک جیسا کیوں نظر نہ آئے گا؟ سلسلہ جب دراز ہوا تو نظر سے زاویۂ نظر تک جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے پانچ سیاحوں کا تصور کیا کہ اہرامِ مصر پر پہلی نگاہ پڑتے ہی ان کا تاثر کیا ہوگا۔ پہلے سیاح جس کا میں نے تصور کیا وہ ایک سچا پکا مسلمان تھا۔ میرے کانوں نے اہرامِ مصر پر اس کا یہ تاثر سنا، ’’بڑے بڑے جاہ و حشمت والے بادشاہوں نے مرنے کے بعد عیش و آرام سے رہنے کے لیے یہ شاندار محلات تعمیر کئے تھے۔ کاش وہ ان محلات کے بجائے آخرت کا توشہ جمع کرلیتے!‘‘ دوسرا سیاح جسے میری چشمِ تصور نے اہرامِ مصر کا نظارہ کرتے ہوئے پایا وہ غالی کمیونسٹ تھا۔ اس کا تاثر تھا، ’’مجھے اس خوبصورت سے مخروط کی ہر اینٹ پر بھوکے، کمزور ، مظلوم اور بے سہارا مزدوروں کے خون کے دھبے اور ان کے استحصال کی داستانیں نظر آ رہی ہیں۔‘‘ تیسرا سیاح ایک بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ اہرامِ مصر کو دیکھ کر وہ عش عش کر اٹھا، اس نے کہا، ’’واؤ، کیا خوبصورت ہے یہ۔ پرانے لوگوں میں بھی کتنی عقل ہوتی تھی۔ کیا آرکٹکچر ہے! ڈارلنگ ذرا میری فوٹو لینا۔ میرے خیال میں اگر ہانگ کانگ میں اسی شکل کا ایک ہوٹل کھولا جائے تو وہ خوب چلے گا۔‘‘ میرے ذہن نے جس چوتھے سیاح کو آواز دی وہ ایک مصری قوم پرست تھا۔ اہرامِ مصر پر نظر پڑتے ہی اس کا سینہ ذرا تن گیا، اس نے سر فخر سے اونچا کرکے کہا، ’’یہ ہمارے فرعونوں کا کارنامہ ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔‘‘ آخری سیاح اعتقاداً ایک پوسٹ ماڈرنسٹ نکلا۔ اس کا تبصرہ مجھے خاصا دلچسپ معلوم ہوا۔ اس نے کہا، ’’ حسن ایک قدرِ اضافی ہے، اس کا کوئی کائناتی پیمانہ نہیں ہے۔ کسی کو یہ بے ڈھنگا مخروط خوبصورت لگے تو لگے، میرے لیے تو اس میں اور کسی جوکر کی ٹوپی میں جسامت کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔‘‘ میں چاہتا تو بھانتی بھانتی کے مزید سیاحوں کا تصور کرسکتا تھا لیکن اتنا کافی تھا۔ اس تمام غوروفکر کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا کہ اہرامِ مصر ہر کسی کو ایک جیسا نظر نہیں آئے گا۔ وہ ہر شخص کو ویسا ہی ’نظر‘ آئے گا جیسا کہ اس کا ’نظریہ‘ ہوگا۔
نظریہ کیا ہے؟
رنگ برنگی جھِلّیاں، شیشے کے ٹکڑوں یا مختلف رنگوں کے چشموں سے بچپن میں ہم سبھی نے کھیلا ہوگا۔ ہرے رنگ کی جھِلّی اوڑھ لی جائے تو ہرا ہی ہرا سجھائی دیتا ہے۔ لال رنگ کا چشمہ پہننے والے کے لیے آسمان سے لے کر زمین تک سب کچھ لالہ زار ہوجاتا ہے۔ بس اسی طرح نظریات کو مختلف رنگوں کے چشموں پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ چشمے آنکھوں پر پہنے جاتے ہیں اور نظریات کی عینک دل اور دماغ پر لگی ہوتی ہے۔ چشمے آسانی سے اتارے اور دوبارہ پہنے جاسکتے ہیں، مگر نظریات کی عینک کو اتاردینا ناممکن ہے، اسے بدلنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ چشمہ پہننے والا، اگر چچا چھکن نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ اس نے چشمہ پہنا ہوا ہے مگر نظریات کی عینک کو ہر انسان جان بوجھ کر نہیں پہنتا، بسا اوقات اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کوئی عینک بھی لگا رکھی ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب صورتحال تب پیش آتی ہے جب کوئی بھولا بھالا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی ایک نظریے(مثلاً اسلام ) کی عینک لگا رکھی ہے مگر درحقیقت اس کے دماغ پر کسی دوسرے نظریے کا چشمہ (مثلاً لبرلزم، سیکولرزم، کمیونزم یا ان سب کا ملغوبہ ) چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کل ملا کر یہ کہ انسان ایک نظریاتی جانور ہے۔ ایک کمپیوٹر میں سافٹ ویئر کی جو حیثیت ہوتی ہے ٹھیک وہی حیثیت انسانوں میں نظریے کی ہوتی ہے۔
انگریزی لفظ ’آئیڈیالوجی‘ کا استعمال سب سے پہلے فرانسیسی مفکر ڈیسٹیوٹ ڈی ٹریسی نے اٹھارہویں صدی کی آخری دہائی میں بطور ’سائنس آف آئیڈیاز‘ کے کیا۔ آئیڈیالوجی اس کے لیے اسی طرح ایک علم کا نام تھا جس طرح بائیولوجی ، ژولوجی یا سوشیولوجی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے آئیڈیالوجی کو آئیڈیاز کے علم کے بجائے مخصوص قسم کے آئیڈیاز کے مجموعے کے طور پر پہچانا جانے لگا اور یوں آئیڈیالوجی نظریے کا ہم معنی ہوگیا۔ اس حساب سے نظریہ یا آئیڈیالوجی دراصل سماجی زندگی میں معنی اور اقدار کی دریافت کا نام ہے۔ ہر سماجی گروہ کی کوئی بنیاد ہوتی ہے (مثلاً رنگ، نسل، زبان، جنس، قومیت، یا مذہب وغیرہ)۔ اسی بنیاد پر اس سماجی گروہ کے اساسی نظریہ کی تعمیر ہوتی ہے۔
انسانی زندگی میں نظریات کی کلیدی اہمیت کے باوجود سماجی علوم میں مختلف نظریات پر بحثیں تو ہوتی ہیں لیکن فی نفسہٖ’’نظریہ‘‘ کو موضوع بحث کم ہی بنایا جاتا ہے۔ نظریات کے معنی و مفہوم کے تعلق سے بھی جو بحثیں کی جاتی ہیں وہ اکثر یک رخی اور نامکمل رہ جاتی ہیں۔ نظریات پر جو تنقید کی گئی ہے وہ بھی غلط فہمیوں کی معراج ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ نظریہ فرد کو متعصب بنادیتا ہے لہذا ہمیں نظریات سے اوپر اٹھ کر سوچنا، غور و فکر کرنا، تجزیہ کرنا اور نتائج اخذ کرنا چاہئے۔ اس میں پہلی بات صحیح ہے اور دوسری غلط یا کم از کم ناممکن۔ یہ صحیح ہے کہ نظریہ ایک حد تک فرد کو متعصب بنا سکتا ہے لیکن اس کے حل کے طور پر نظریات سے ’اوپر‘ اٹھ جانا ممکن نہیں۔ ہر فرد کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔دوسرے الفاظ میں ہر فرد کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی غیر جانبدار نہیں ہے، غیر جانبداری کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ پھر تعصب سے بچنے کا طریقہ کیا ہو؟ تعصب کے مضر اثرات سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے تعصبات کو علی الاعلان تسلیم کرلیا جائے۔ وگرنہ ایک فرد خود کو غیر جانبدار کہے گا مگر اس کے خیالات مارکسزم کا چربہ ہوں گے؛ دوسرا خود کو نظریات سے اوپر کی چیز قرار دے گا مگر اس کی پوری فکر لبرل ہو گی۔ بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کسی ایک نظریے کو فی نفسہ قبول نہیں کرتے مگر مختلف نظریات سے مختلف تصورات ادھار لے لیتے ہیں۔ ایسے افراد کا نظریہ خود ساختہ ہوتا ہے یہ کہنا تو صحیح ہے لیکن ایسے افراد کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا یہ حقیقت کی بالکل غلط ترجمانی ہے۔
نظریہ کی تعریف میں بھی لوگوں نے نظریہ کے مثبت یا منفی اثرات سے بحث کی ہے اس بات سے نہیں کہ نظریہ کہتے کسے ہیں۔ خال خال ہی مارٹن سیلیگر جیسے مفکر نظر آتے ہیں جو نظریہ کی تعریف بیان کرنے میں کامیاب ہیں۔ اپنی کتاب آئیڈیالوجی اینڈ پالیٹکس میں سیلیگر لکھتے ہیں کہ ’’نظریات کچھ ایسے عقائد و اقدار کا نام ہے جو افراد کو عمل پر آمادہ کردیں۔‘‘ مارٹن سیلیگر نے نظریے کی اس مختصر مگر جامع تعریف میں تمام جہتوں کا لحاظ کیا ہے۔ ایک ایسی فکر جس کے ساتھ عمل یا عمل کے لیے کوئی تحریک نہ ہو فلسفہ تو ہوسکتا ہے نظریہ نہیں۔ ایک ایسا عمل جس کے پیچھے کوئی فکر نہ ہو ایکٹوزم تو ہوسکتا ہے مگر نظریہ نہیں۔ نظریہ اسی شئے کا نام ہوسکتا ہے جو بیک وقت فرد اور سماج کو فکر بھی دے اور عمل کا پیغام بھی۔ ان مبسوط معنوں میں نظریے کو ’’ایمان‘‘ سے تشبیہہ دی جاسکتی ہے۔
نظریہ کا کام کیا ہے؟
نظریے کی حیثیت ایک فرد کی زندگی میں وہی ہے جو ایک انجان شہر میں اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں کسی اجنبی مسافر کی جیب میں موجود نقشے کی ہوتی ہے۔ ایک عام قسم کا نقشہ،جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کسی علاقے کا علامتی خاکہ ہوتا ہے جس میں اس علاقے کے اسپتال، پولس تھانہ، ہوٹل، عبادت گاہیں، تاریخی مقامات، اور سڑکوں وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے تاکہ ڈھونڈنے والا اپنے اور اپنی منزل کے محلِ وقوع کا اندازہ لگاسکے۔ نقشہ زمین پر موجود ہر ہر عمارت اور ہر ہر گلی کو نہیں دکھاتا، نہ ہی اس میں اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ نقشہ کا کام ایک ایک سینٹی میٹر میں میلوں کے فاصلے کو قید کرنے کا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسافر ’زمینی‘ حقائق کو نقشے (یا نظریے) سے ’مختلف‘ پاتے ہیں اور جل بھن کر تھیوری اور پریکٹس کی دوئی پر سمع خراشی کرتے ہیں۔ صحیح نقشہ ہو یا صحیح نظریہ، زمینی حقائق اس سے ’زائد‘ تو ہوسکتے ہیں اور ہوتے ہی ہیں لیکن ’مختلف‘ نہ ہوتے ہیں نہ ہوسکتے ہیں۔ انسانی دنیا میں البتہ ایسے بیوقوف ایک ڈھونڈیے تو ہزار مل جائیں گے جو واشنگٹن یا ماسکو کے نقشے سے دہلی میں منزل کا پتہ کھوجتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ واشنگٹن کا بہترین سے بہترین نقشہ بھی دہلی میں منزل کی رہنمائی کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ ایسے خوش فہم مسافروں کو جب تلاشِ بسیار کے باوجود دہلی میں واشنگٹن کی سڑکیں، ہوٹل اور عمارتیں نہیں ملتیں تو وہ گھوم پھر کر اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اچھی طرح ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں وگرنہ نقشے میں بذات خود کوئی خامی نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ تب آتا ہے جب کوئی خوش فہم مسافر بلا کسی دلیل کے جامع مسجد کو واشنگٹن کا اسلامک سینٹر گردان کر آس پاس کے علاقوں کو نقشے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں ناکامی، جو کہ ایسے مسافر کا مقدر ہے ، بھی اس کوڑھ مغز کی آنکھوں پر پڑے پردے کو ہٹانے میں ناکام رہتی ہے۔ وہ پھر سپریم کورٹ کو وہائٹ ہاؤس قرار دے کر نئے سرے سے اپنی تلاش میں مگن ہوجاتا ہے۔ یوں بھٹکنے بھٹکانے کا یہ سلسلہ تاعمر جاری رہتا ہے۔
ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مختلف نظریات، مختلف مفکرین کے ذہنوں کی اپج ہوتے ہیں۔ ایک مفکر پھر چاہے وہ کتنا ہی علامۃ الدہر کیوں نہ ہو وہ جن مسائل سے تعرض کرتا ہے اور ان کے جو حل سجھاتا ہے ان کی افادیت کا ایک محدود سیاق اور دائرہ ہوتا ہے جس کے باہر اس کے نظریے کی کوئی افادیت نہیں ہوتی۔ اکثر نظریات اور فلسفے تو عملی میدان میں قدم ہی نہیں رکھتے بلکہ نرے ’نظریات‘ اور ’فلسفے‘ ہی رہ جاتے ہیں۔ کچھ جو عملی دنیا میں رہنمائی کا بیڑا اٹھاتے ہیں وہ یا تو اول وہلے میں ہی منہ کی کھا جاتے ہیں یا پھر کمیونزم کی طرح ہر ٹھوکر کے بعد کسی نہ کسی قسم کی پیوندکاری کے ذریعہ ماسکو کے نقشے سے کبھی کلکتہ کبھی ڈھاکہ تو کبھی بیجنگ میں راستہ کھوجتے رہتے ہیں۔
مختصر الفاظ میں نظریات کے بنیادی کام دو ہیں۔ ان کا پہلا کام یہ ہے کہ حق، خیر اور حسن کے تعلق سے کچھ مخصوص تصورات کو فروغ دے کر انہیں بنیادی اور عالمگیرباور کرایا جائے اور ان تصورات کو کچھ اس طرح naturalise کیا جائے کہ وہ معاشرے کاcommon sense بن جائیں۔ نظریات کا دوسرا کام مخالف نظریات اور ناپسندیدہ تصورات کو غلط ثابت کرکے ان کی بیخ کنی کرنا یا کم از کم ان کا مٍذاق اڑاکر نظرانداز کرنا ہے۔ مختصراً یہ کہ نظریہ فرد اور سماج کے لیے حق کا ایک معیار مقرر کرتا ہے۔ پھر دوسرے نظریات پر تنقید کرکے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نظریے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بڑھنا پھلنا پھولنا چاہتا ہے چنانچہ وہ عامۃ الناس کو خود کی طرف دعوت دیتا ہے، اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کو جمع ہوکر ایک طے شدہ مقصد کے لیے جدوجہد کی راہ سجھاتا ہے۔ یہ طے شدہ مقصد عموماً موجودہ دنیا سے مختلف مثالی دنیا کا ایک تصور ہوتا ہے جس کے قیام کے لیے موجودہ دنیا کی کمان سنبھال کر اس کو بدلنا ضروری قرار پاتاہے۔ ایک جملے میں کہیں تو اس جدوجہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظریۂ موصوف کی بالادستی قائم ہوجائے۔ غلبہ و استیلا کی اس خواہش سے کوئی نظریہ مستثنیٰ نہیں ہے۔
انسانی زندگی پرنظریہ کے اثرات
نظریات کے اثرات ایک فرد کے ذہن اور سماج کے مزاج پر کیسے مرتب ہوتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے شاید ایک مثال ممد و معاون ثابت ہو۔ سرکس میں کرتب دکھانے والے ہاتھیوں کو سدھانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ وہ پالتو ہاتھی جو چڑیا گھر میں انسانوں کی صحبت میں پیدا ہوں اور پرورش پائیں وہ تو غلام ابن غلام ہوتے ہیں، انہیںسدھانا مشکل نہیں۔ مگر جب جنگل کے آزاد منش اور قلندر قسم کے ہاتھی کو پکڑنا ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ ہاتھی کانوعمر بچہ ہاتھ لگے۔ کیوں؟ بات واضح ہے کہ آزادی کا تصور بڑے ہاتھی میں اس حد تک راسخ ہوتا ہے کہ اسے غلامی کا پاٹھ پڑھانا اور اس پر مستزاد یہ کہ اسے کرتب سکھانا اور پھر دکھانے پر آمادہ کرلینا جان جوکھوں کا کام ہے۔ البتہ جونیئر ہاتھی کو ’تعلیم و تربیت‘ سے آراستہ کرنا نسبتاً آسان ہے۔ ’آسان‘ اپنے آپ میں ایک اضافی قدر ہے۔ اس پر یہاں ’نسبتاً‘ کا اضافہ دانستہ کیا گیا ہے کیونکہ جس چیز کو آسان کہا گیا ہے اس آسانی کا حال یہ ہے کہ اس بیچارے ہاتھی کے بچے کو دو مضبوط کھمبوں یا درخت کے تنوں کے بیچ موٹی موٹی زنجیروں سے کچھ اس طرح باندھ دیتے ہیںکہ وہ حرکت بھی نہ کرسکے۔ وہ تڑپتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ آزادی کے لیے بھرپور جدوجہد کرتا ہے، اپنی پوری قوت مجتمع کرکے زور لگاتا ہے کہ کسی طرح ان زنجیروں سے چھٹکارہ ملے مگر اس کی ایک نہیں چلتی۔ ہفتے عشرے میں اس کی ناکام کوششیں اسے مایوس کردیتی ہیں، اسے سمجھ میں آجاتا ہے کہ اب غلامی ہی اس کا مقدر ہے۔ بھوک پیاس کی شدت سے نڈھال یہ ہاتھی کا بچہ جیسے ہی مایوسی کے عالم میں زور لگانابند کردیتا ہے تو غلامی پر رضامندی کے ’انعام‘ کے طور پر اسے کھانے کے لیے مرغوبات دیے جاتے ہیں۔ دھیرے دھیرے موٹی زنجیروں کی جگہ موٹی رسیاں لے لیتی ہیں۔ اس ہاتھی کے بچے کو غلام ہاتھیوں کی صحبت میں رکھا جاتا ہے تاکہ غلامی کے آداب و تہذیب سے کماحقہ واقفیت حاصل کرلے۔ کچھ تو آزادی سے مایوسی، کچھ غلاموں کی صحبت اور کچھ غلامی کی تن آسانی۔۔۔ ہاتھی کے بچے کو غلامی راس آجاتی ہے اور اس کی باقاعدہ ٹریننگ کاآغاز ہوتا ہے۔ ہاتھی کا بچہ بڑا ہوکر ایک مستنڈا ہاتھی بنتا ہے۔ وہ لحیم شحیم ہاتھی جسے بچپن میں قابو کرنے کے لیے موٹی موٹی زنجیریں درکار تھیں اب اسے ایک پتلی سی رسی سے باندھ دیا جاتا ہے اور وہ چوں تک نہیں کرتا۔
مسلم امت کو آج اسی غلام ہاتھی پر قیاس کر لیجئے۔ پچھلے دو تین صدیاں ایسی گزری ہیں جب مسلمانوں اور یورپی طاقتوں میں بالادستی کی جنگ چل رہی تھی۔ یہ جنگ میدانِ کارزار کے ساتھ ساتھ میدانِ افکار و اکتشاف میں بھی جاری و ساری تھی۔ یہ جنگ تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر ہورہی تھی جب مسلم امت اس گیند کی طرح تھی جسے پھینکنے والے نے بہت اونچا پھینکا تھا مگر اب اپنے نقطہ عروج پر پہنچنے کے بعد وہ روبہ زوال تھی۔ اس کے مقابلے میں یورپ میں نشاۃ الثانیہ کا دور تھا۔ یورپی تازہ دم اور نئے جوش و خروش سے سرشار تھے۔ وہ ماضی میں گم نہیں بلکہ مستقبل کے لیے سرگرداں تھے۔ ان کی تہذیبی گیند گو مسلم امت کی روبہ زوال گیند سے نیچے ہی تھی مگر لگاتار اوپر کا سفر طے کررہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کشمکش کا نتیجہ یورپ کی علمی و سیاسی بالادستی کی صورت میں مسلم امت کے سامنے آیا۔ ہر محاذ پر خونریز مقابلہ آرائی ہوئی لیکن کب تک؟ آخر کار مسلم امت اور اس کے قائدین کے سامنے دو ہی متبادل رہ گئے، غلامی کی خلعتِ فاخرہ یا آزادی کا کفن۔ کسی نے پہلے تو کسی نے دوسرے کو ترجیح دی۔ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ مگر دنیاوی نتیجہ ہر دو کا ایک تھا۔ محکومی اور غلامی۔ مگر آج حالات بدل چکے ہیں۔ دنیا بھر میں تحریکاتِ اسلامی کی بیش بہا کاوشوں کے نتیجے میں آج کا مسلمان بیدار ہورہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے ہتھیار خود دشمنانِ اسلام کے لیے ناقص اور نقصاندہ ثابت ہورہے ہیں۔ مغربی تہذیب خود برطانیہ اور امریکہ میں اسلام کے فروغ خصوصاً خواتین میں اسلام کی بڑھتی مقبولیت سے خائف ہے۔ ہر سو مغربی تہذیب کے زوال کا چرچا ہے۔ فرید زکریا جیسے امریکہ پرست بھی پوسٹ امریکن ورلڈ آرڈر کی بات کررہے ہیں۔ یہ دراصل دبی زبان میں پوسٹ ویسٹرن ورلڈ آرڈر کا اقرار ہے۔ لیکن اس پوری گہماگہمی میں، جس میں مسلم ممالک میں آئی اسلامی بیداری اور عرب بہاریہ بھی شامل ہے، ہمارے قائدین، رہنماؤں، بادشاہوں کا حال کیا ہے؟ ان کا حال اس ہاتھی کا سا ہے جو بچپن میں فوجی قوت کے بل پر سیاسی غلامی کی زنجیروں میں کچھ ایسا کس کر جکڑ دیا گیا تھا کہ سیاسی غلامی کی وہ زنجیریں کٹ جانے کے باوجود معیشت، تہذیب اور ذہنی غلامی کی پتلی سی رسی سے بندھا ہوا ہے، اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اسے اپنی آزادی کا نہ یقین ہے کہ نہ اس کی کسک۔ یہ اسی ذہنی غلامی کا شاخسانہ ہے کہ آج ہمارے دانشور حضرات خود بدلنے کے بجائے قرآن کو بدل دیتے ہیں، اسلام آج بھی قابل عمل ہے اس بات کے ثبوت میں وہ فوراً اسلام کو عین سوشلزم، لبرلزم یا سیکولرزم باور کرانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی کوئی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسلام میں ’بھی‘ آزادی ہے، اسلام میں ’بھی‘ مساوات ہے، اسلام میں ’بھی‘ رواداری ہے اور اسلام دہشت گردی کا علمبردار نہیں یہ کہتے کہتے ان کی زبان نہیں سوکھتی۔
اطالوی مفکر گرامسی کے مطابق نظریہ فرد کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو کچھ اس طرح سلب کرلیتا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی مفادات تک نظر نہیں آتے۔ گرامسی کی یہ تھیوری Cultural Hegemony کہلاتی ہے۔ دراصل گرامسی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے تھے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے صنعتی ممالک میں جہاں مارکس کے مطابق اشتراکی انقلاب کا ظہور سب سے پہلے ہونا چاہئے تھا وہ کیوں نہ ہوسکا۔ گرامسی کے مطابق ایسا اس لیے ہوا کہ وہاں کی انقلابی طاقت، یعنی مزدور، خود بورژوا نظریۂ حیات اور تہذیبی غلامی کا شکار ہوگئی اور ایک نئے نظریے کی بنیاد پر ایک نئی دنیا کی تعمیر کا خواب بھلادیا۔ نظریات کے تعلق سے کچھ اسی قسم کی بات فرانسیسی فلسفی مشل فوکو بھی کہتے ہیں۔ فوکو کے مطابق نظریات کی بنیادی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی تصورحقیقت پر منحصر ہوتے ہیں۔ حق کا یہ تصور ہی ان کی بنیاد ہوتا ہے۔ چونکہ ایسے کسی ازلی و ابدی حق کا وجود ہی نہیں ہے اور تمام ’حقائق‘ اضافی ہیں اس لیے تمام نظریات اپنی جڑ بنیاد ہی سے غلط ہوتے ہیں۔ نظریات لوگوں کو قابو میں کرنے کے لیے مذہب کی طرح گڑھے جاتے ہیں۔ یہ سماج میں کچھ چیزوں کو منطقی اور طبعی قرار دیتے ہیں اور اسی مناسبت سے دیگر چیزیں غیرمنطقی و غیرطبعی قرار پاتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں نظریات کا کام normalisation ہوتا ہے۔ ایک مخصوص نظریہ ایک مخصوص تصور حیات کو عوام کا common sense بناکر پیش کرتا ہے اور یہی نظریات کا اصل کام ہے۔
کیا نظریات کا دور ختم ہوچکا ہے؟
سویت یونین کے زوال کے بعد مغربی دانش گاہوں نے زوروشور سے اس خیال کا پروپگینڈا شروع کیا ہے کہ نظریات کا دور اب ختم ہوچکا ہے۔ فرانسس فوکویاما نے The End of History and the Last Man میں اس خیال کا اظہار کیا کہ نظریات کے اس دور کا خاتمہ لبرل ڈیموکریسی اور سرمایہ داریت کی دیگر نظریات پر فتح کی وجہ سے ہوا ہے۔ شہرہ آفاق کتاب The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order کے مصنف سیموئیل پی ہنٹنگٹن اس فکر کے سب سے معروف ترجمان ہیں۔ انہوں نے تہذیبوں کے تصادم کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کمیونزم کے علمبردار سویت یونین کے زوال کے ساتھ ہی نظریات کے تصادم کا دور ختم ہوچکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بین الاقوامی معاملات کے اس دانشور کے نزدیک نظریات کا دور ختم ہوچکا ہے یا اب اسے ایک major player کی حیثیت حاصل نہیں ہے اور آج دنیا کی توجہ کا مرکز نظریات نہیں بلکہ غربت، ماحولیات، تعلیم، اور ترقی وغیرہ ہیں یا ہونے چاہئیں۔ہنٹنگٹن کی کتاب سے یہ جو نتیجہ ہم نے اخذ کیا ہے،حامد دباشی عرب بہاریہ کے تناظر میں اسی کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنی کتاب The Arab Spring: The End of Post-Colonialism میں وہ کہتے ہیں کہ عرب بہاریہ کا نہ تو کوئی لیڈر تھا اور نہ ہی کوئی نظریہ۔ حامد دباشی کا اصرار ہے کہ عرب بہاریہ کسی نظریاتی تحریک کا نتیجہ نہیں بلکہ خود نظریات کے خلاف ایک تحریک ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ ’’عرب بہاریہ کسی ایک نظریے کی حقانیت نہیں بلکہ ہر نظریے سے آزادی کا پیغام ہے۔‘‘ اور یہ کہ عرب بہاریہ کے ذریعہ دنیا ایک مابعد نظریاتی دور (Post-Ideological Phase) میں داخل ہوچکی ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام نظریات پھر چاہے وہ تیسری دنیا کا سوشلزم ہو یا استعمار مخالف نیشنلزم یا انتہا پسند اسلامزم، سب فضول ہوچکے ہیں۔اسی دور میں نظریہ کی ضرورت کے انکار اور اس پر تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ نظریہ پر تنقید کے لیے عموماً دو قماش کی دلیلوں کا سہارا لیا گیا۔
اول: یہ کہا گیا کہ نظریات عملی نہیں ہوتے صرف خیالی اور فلسفیانہ ہوتے ہیں اور ان کا بڑبولا پن عملی میدان میں آتے ہی پھس ہوجاتا ہے۔ مثلاً(الف) گاندھی کی مشینوں اور ٹکنالوجی یہاں تک کہ ریل گاڑی پر نظریاتی تنقید یا عدم تشدد کا نظریہ جس کے مطابق ملک کی فوج ہونے کی ضرورت سے بھی انکار(ب)مارکس کا ایک ایسے مثالی سماج کا تصور جہاں نہ ریاست ہو، نہ حکومت ہو، نہ امیر، نہ غریب اور نہ طبقاتی کشمکش(ج) انارکزم کا ایک ایسے سماج کا تصور جہاں نہ کوئی حکومت ہو نہ کوئی پولس اور ہر فرد آپ اپنا نگراں ہو، وغیرہ
کل ملا کر یہ کہ نظریات بہت ہی حسین خواب دکھاتے ہیں مگر ان کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ حقیقت سے فرار اور یوٹوپیا سے عشق نظریات کی سرشت میں شامل ہے۔ نظریات کا یہ بڑبولاپن اس بات کا غماز ہے کہ نظریات ذہنی عیاشی کی حد تک تو ٹھیک ہیں لیکن عملی دنیا میں اگر انہیں نافذ کردیا جائے یا نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا کا کاروبار چند لمحے بھی نہ چل سکے۔ مختلف نظریات پر غیر عملی ہونے کی جو پھبتی کسی جاتی ہے اس میں بہت حد تک صداقت ہے۔ لیکن اس اعتراف کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ نظریہ پر غیر عملی ہونے کی تنقید دراصل کچھ نظریات پر تنقید ہے جو ہر نظریے پر صادق نہیں آتی۔ یہ ثابت کردینے سے کہ شیر کا گوشت حرام ہے، ہاتھی کا گوشت حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سرے سے ’’گوشت‘‘ ہی حرام ہے۔
دوم: یہ کہا گیا کہ نظریات کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ ’غلط‘ ہوتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس تنقیدی نہج کی شروعات کرنے والے فریڈرک اینجلز کے مطابق نظریات ’’غلط شعور‘‘ (False Consciousness) ہوتے ہیں۔ یعنی کسی نظریے پر ’ایمان‘ لانے میں اس کے ’مومن‘ کی نیت درست ہوتی ہے البتہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس نظریے پر وہ ایمان لایا ہے وہ بجائے خود غلط ہے۔ یہاں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ یہ تنقید کرتے وقت شاید اینجلز کو اندازہ نہیں تھا کہ مارکسزم کو بھی کسی زمانے میں نظریے کی حیثیت حاصل ہوگی اور اینجلز کی تعریف کے مطابق اسے بھی ’’غلط شعور‘‘ قرار دینا پڑے گا۔ دراصل ایک کا نظریہ دوسرے کے لیے ’’غلط شعور‘‘ ہواکرتا ہے۔ اینجلز کے لیے اگر دوسرے نظریات ’’غلط شعور‘‘ ہیں تو دوسرے نظریات کے ماننے والوں کے لیے مارکس اور اینجلز خود ’’غلط شعور‘‘ کا شکار تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جرگن ہیبر ماس کا ماننا ہے کہ، ’’مختلف نظریات اور تصورِ نظریہ پر تنقید یہ دونوں ہم عمر ہیں۔‘‘ سادے الفاظ میں: نظریہ پر کی جانے والی تنقید بھی درحقیقت نظریاتی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے تازہ مثال پوسٹ ماڈرنزم ہے جو ماڈرن زمانے میں موجود تمام نظریات کے ابطال بلکہ ہر کائناتی اور عالمگیر حقیقت اور تصور حقیقت کو جھٹلانے کے لیے میدان میں اترا تھا۔ تمام نظریات تو کیا خاک ختم ہوتے البتہ دانشورانہ حلقوں میں پوسٹ ماڈرنزم کو خود ایک نظریے کے طور پر قبول کرلیا گیا۔ یوں بت شکنی کا دعوی کرنے والا خود بت بن بیٹھا۔
اسلام بحیثیتِ نظریہ
اسلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک دین ہے، ایک مکمل نظریۂ حیات ہے۔ بطور نظریہ اگر اسلام کا جائزہ لیا جائے تو ہم اس میں مندرجہ ذیل اہم خصوصیات پاتے ہیں:
(۱)انسانی عقل باوجود اپنی بیکرانی کے محدود ہے۔ عمانویل کانت کے بعد مغربی فلسفہ بھی اس محدودیت کا قائل ہے۔ یہ منطقی بات ہے کہ جب انسانی عقل اپنے سیاق، ماحول اور تاریخ سے محدود ہوتی ہے تو اسی انسانی عقل کے ذریعہ کسی ایسے نظریہ کی ایجاد کی توقع رکھنا جو رنگ، نسل، جنس، وطن، زبان اور زمان و مکان کے تمام تر اختلافات کے باوجود یکساں قابل عمل ہو، ایک غیر عقلی اور غیر فطری توقع ہے۔ لہذا اسلام ، دوسرے نظریات کے برعکس، اس دعوے کے ساتھ اپنا نظریہ پیش کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ خالقِ کائنات کی طرف سے بھیجا ہوا نظام ہے۔مختصر یہ کہ اسلام انسانی عقل کو ایک صحیح نظریۂ حیات کو گھڑنے کی نہیں بلکہ اس کو پہچاننے کی ذمہ داری دیتا ہے۔
(۲) ایک ناقابلِ عمل یوٹوپیا ہونے کی تہمت اسلام پر نہیں لگائی جاسکتی کیونکہ اسلام دنیا کا واحد نظریہ ہے جو اپنی تاریخ میں چالیس سال کا ایسا مثالی دور رکھتا ہے جس کے بھلے برے کی پوری ذمہ داری لینے کے لیے وہ تیار ہے۔ دیگر نظریات کے پاس صرف مفروضات اور یوٹوپیا ہیں، زمین پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اپنا کوئی ایسا مثالی ماڈل پیش نہیں کرسکے، جس کی ذمہ داری وہ بلا جھجک قبول کرسکیں۔ پچھلی صدی میں کہا گیا کہ سویت یونین کمیونزم کا اور اسرائیل یہودیوں کا آئیڈیل اسٹیٹ ہے آج تقریباً سارے کمیونسٹ اور یہودیوں کی اکثریت اس دعوے کو شد و مد سے رد کرتی ہے۔
(۳) نظریہ اپنے ماننے والوں میں ایک آنے والے کل کی امید جگاتا ہے۔ اس نئے سویرے کے لیے لڑنے اور قربانیاں دینے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لڑائی میں کامیابی کا یقین دلاتا ہے کہ کامیابی کا یقین نہ ہو تو لڑائی جیتنا تو دور لڑنا بھی محال ہوجاتا ہے۔ اسلام میں کامیابی کا یہ تصور بھی جو اپنے ماننے والوں میں عمل کے لیے مہمیز کرتا ہے دیگر نظریات سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ اسلام کامیابی کا دوسطحی تصور پیش کرتا ہے۔ پہلی سطح کی کامیابی باطل پر حق کی فتح اور غلبے کے نتیجے میں اجتماعی طور پر اس دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ دوسری سطح پر کامیابی فرد کو اپنے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی رضا کی صورت میں آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ پہلی سطح کی جدوجہد میں اسلام اپنے ماننے والوں کو نتیجے کا نہیں بلکہ نیت اور کوششوں کا مکلف کرتا ہے جس سے ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں۔ صحیح سمت میں جی توڑ کوشش پہلی سطح پر اسے کامیابی دلائے نہ دلائے، دوسری سطح کی کامیابی جو کہ اصل کامیابی ہے وہ اسے حاصل ہوکر رہتی ہے۔
(۴) اسلام دین فطرت ہے اس لیے وہ انسانی عقل اور جذبات دونوں کو اپیل کرتا ہے۔ بحیثیت نظریہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی اس کا اعتدال ہے۔ مثال کے طور پر سرمایہ دارانہ نظام فرد کی بے قید آزادی کا قائل، انفرادیت پسندی کا علمبردار اور بازار میں حکومت کی کسی قسم کی مداخلت کے خلاف ہے۔ نتیجہ؟ سود کا پھیلا ہوا جال، دولت کا ارتکاز، فاقہ کشی، خود کشی، جنسی انارکی، بکھرتے خاندان وغیرہ وغیرہ۔ وہیں کمیونزم انسانوں میں جبری مساوات اور فرد پر جماعت کی ترجیح اور کلیت پسندی کا علمبردار ہے۔ نتیجہ؟ بدترین آمریت،صلاحیتوں کی ناقدری، کاہلی اور نااہلی کا دوردورہ، سزائے موت، ملک بدری ، جنسی انارکی، بکھرتے خاندان وغیرہ وغیرہ۔ ان دونوں نظریات کی انتہاؤں کے بالمقابل ، اسلام انسانوں میں بنیادی مساوات کا قائل ہے یعنی ہر انسان، انسان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کے برابر ہے۔ اس برابری میں یہ بات شامل ہے ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہئے، اگر کوئی انسان کسی وجہ سے اپنی بنیادی ضروریات کی تکمیل سے قاصر ہے تو یہ اجتماعیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پورا کرے۔ اس بنیادی مساوات کے بعد اسلام فرد کی خلاقانہ صلاحیتوں پر قدغن نہیں لگاتا بلکہ اپنے جوہر دکھلانے کے لیے اسے ایک وسیع میدان فراہم کرتا ہے۔ اگر صرف کمانے کی مثال لی جائے تو اسلام فرد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مزاج اور صلاحیتوں کے مطابق کمائے، جتنا چاہے کمائے، شرط صرف اتنی ہے کہ وہ جو کچھ کمائے حلال راستے سے کمائے اور حلال راستے سے خرچ کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اسے سود، شراب، سگریٹ، تمباکو، جوا، قحبہ خانے اور فحش فلموں وغیرہ کے کاروبار کرکے پیسہ بٹورنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسے اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ان پابندیوں کے ساتھ وہ جو کچھ کمائے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ پھر دولت گردش میں رہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے فرد کے مرنے کے بعد اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم کردیا جائے گا۔ اسی طرح قوم پرستی (Nationalism)اور نسل پرستی (Racism)کی مثال لی جاسکتی ہے اول الذکر چند پہاڑوں اور ندیوں یا نقشے پر خود انسان کی کھینچی ہوئی فرضی لکیروں کی بنیاد پر انسانیت کی تقسیم کا قائل ہے۔ آخر الذکر نسل کی بنیاد پر گروہ بندی کا قائل ہے۔ دونوں صورتوں میں فضیلت کا معیار انسان کی کسی مخصوص ملک یا نسل میں پیدائش ہے جو یقینا حادثاتی ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل اسلام جغرافیائی نہیں بلکہ فکری قومیت کا علمبردار ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ فرد کی اپنے وطن، اپنی نسل، اپنی قوم، اپنی زبان سے محبت قدرتی ہے اور ضرور ہونی چاہئے لیکن یہ محبت عصبیت بن کر حق و باطل کا معیار نہ بن جائے۔اسلام فضیلت کے صرف ایک معیار کو تسلیم کرتا ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ کسی مخصوص قوم یا نسل یا ملک میں حادثاتی طور پر پیدائش اسلام کے نزدیک کوئی معیارِ فضیلت نہیں ہے۔
الغرض بحیثیت نظریہ اسلام کی حیثیت سب سے انوکھی اور نرالی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نظریات کو نقشوں سے تشبیہہ دی جاسکتی ہے۔ اس حساب سے بھی اسلام دیگر نظریات (نقشوں) سے ممتاز ہے جنہیں زمان و مکان کی قید میں محصور چند انسانوں نے اپنے محدود علم اور ناقص تجربات کی بنیاد پر بنالیا تھا اور اپنی ناواقفیت یا کم علمی کی بنا پر انہوں نے یا ان کے متبعین نے یہ سوچ لیا کہ ان کا بنایا ہوا ایک مخصوص علاقے کا نقشہ دنیا بھر میں منزل تک رہنمائی کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ اسلام تو خالق کائنات کا بنایا ہوا ’نقشہ‘ ہے جسے دنیا کے کسی نقشے سے اگر کسی حد تک تشبیہہ دی جاسکتی ہے تو وہ Google Earth ہے جس کے ذریعہ آپ دنیا بھر میں اپنی منزل تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ اپنی پرانی مثال کی طرف لوٹیں تو ہر انسان کی نگاہوں پر باضابطہ یا بے ضابطہ طور پر کسی نہ کسی نظریے کا چشمہ چڑھا ہوا ہے۔ اس سے کسی انسان کو مفر نہیں ہے۔ مگر اسلام ایک ایسا چشمہ ہے جس کا انتخاب فرد پورے ہوش و حواس میں خود کرتا ہے اور یہ جان کر (بسا اوقات آزما کر) کرتا ہے کہ یہ وہ واحد چشمہ ہے جس کا شیشہ صاف و شفاف ہے، جو ہمیں دھوپ اور دھول سے ضرور بچاتا ہے لیکن لال کو لال ، کالے کو کالا، حق کو حق اور باطل کو باطل ہی دکھاتا ہے۔ جیسا کہ مومنین کو دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللھم ارنی الاشیاء کما ھی (اے اللہ ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں) یا اللھم ارنی الحق حقاً والرزقنا اتباعا، اللھم ارنی الباطلا باطلاً والرزقنا الجتنابا (اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کی توفیق بخش) !
کرنے کا کام
سماجی علوم ہمیں سماج کو پڑھنا اور سمجھنا سکھاتے ہیں۔ ان میںپڑھائے جانے والے اصولوں کی حیثیت سماج کے لیے کلیدی ہوتی ہے۔ یہ مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور ان مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ کار کی نشاندہی بھی۔ لیکن کیا یہ سماجی علوم تعصب سے پاک ہیں؟ عمانویل والرسٹین نے اپنے مقالےEurocentrism and its Avatars: The Dilemmas of Social Scienceمیں اس سوال کا جواب نفی میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ’’سماجی علوم کا وجود یورپی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہوا، تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر جب یورپ پوری دنیا کے نظام پر حاوی تھا۔ اس لیے طبعی طور پر سماجی علوم کے مباحث کا انتخاب، انہیں برتنے کے آداب، تحقیق کے طریقہ کار اور سماجی علوم کے نظریۂ علم (epistemology) سبھی پر اس ماحول کی گہری چھاپ ہے جس ماحول میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ ‘‘ والرسٹین نے صاف کہا ہے کہ یہاں یورپ سے اس کی مراد نقشے پر موجود کسی جگہ سے زیادہ ایک تہذیب اور ایک فکر ہے۔ مختصر الفاظ میں سماجی علوم عالمگیر اصولوں پر مبنی نہیں ہیں جیسا کہ دعوی کیا جاتا ہے بلکہ ان تصورات اور توجیہات پر منحصر ہیں جن کے ڈانڈے مغرب کے نظریۂ حیات سے جاملتے ہیں۔ والرسٹین کے مطابق سماجی علوم کو اس یورپی چنگل سے چھڑانا ایک عظیم علمی خدمت ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان کام ہے؟ نہیں، اس راستے میں چیلنجز بیشمار ہیں۔ خود والرسٹین ہمیں سب سے بڑے خطرے سے ان الفاظ میں آگاہ کرتے ہیں:
ایشیا اور افریقہ کے ممالک جیسے جیسے آزاد ہوئے ہیں اس کے علمی دنیا پر بھی اسی طرح اثرات ہوئے ہیں جس طرح سیاسی دنیا پر۔ ایک بڑی تبدیلی جو ہوئی ہے وہ یہ کہ سماجی علوم کا Eurocentrism کڑی تنقید کے نشانے پر ہے۔ یہ تنقید فی الواقع صحیح ہے، اور یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اگر سماجی علوم کو اکیسویں صدی میں کوئی ترقی کرنی ہے تو اسے اپنے اس Eurocentric ورثے سے نجات حاصل کرنی ہوگی جس نے سماجی علوم کے تجزیوں کو مسخ کردیا ہے کہ موجودہ دور کے فہم اور اس دور کے مسائل کے حل دریافت کرنے میںیہ یکسر ناکام ہے۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ یہ Eurocentrism کس بلا کا نام ہے۔ یہ ایک بیشمار سروں والا عفریت ہے اور اس کے کئی اوتار ہیں۔ اس ڈریگن کو یوں آسانی سے ماردینا ممکن نہیں ہوگاکیونکہ اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو Eurocentrism پر تنقید کا ہم نام تو لیں گے لیکن اس پر تنقید کرتے ہوئے ہم انہی Eurocentric تصورات کا استعمال کربیٹھیں گے جس کا سیدھا نتیجہ حلقۂ دانشوران پر ان تصورات کی گرفت اورمستحکم ہوجائے گی۔
ایک ایسے زمانے میں مغرب پر کی جانے والی تنقید بھی مغرب کے نظریات کی خوشہ چیں ہے۔ جب نظریات کی اہمیت کو کم کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ علمی دنیا کا اس بات پر اجماع ہوگیا ہے کہ دنیا میں اب نظریاتی سطح پر لبرل ڈیموکریٹک کیپیٹلزم کا کوئی مخالف نہیں رہ گیا ہے اسلامی نظریے کو ماننے والوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ سماجی علوم میں اجتہادی مہارت کا حصول اور مروجہ سماجی علوم کا تحقیقی و تنقیدی تجزیہ کر کے ایک نئی نظریاتی بحث کو شروع کرنا ایک ایسا کام ہے جس سے بڑا فکری احسان آج کی دنیا پر نہیں کیا جاسکتا۔ اس نظریاتی بحث کو مندرجہ ذیل خطوط پر آگے بڑھایا جاسکتا ہے:
(۱)ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہر انسان کی نگاہوں پر کسی نہ کسی نظریے کا چشمہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔
(۲) بیرونی حقائق ہمیں اپنے نظریات کے مطابق نظر آتے ہیں۔ بالفاظ دیگر سامنے موجود شئے کا رنگ اور اس کی جسامت ہمیں اپنے چشمے کے رنگ اور نمبر کی مناسبت سے نظر آئے گی۔
(۳)عام طور پر لوگ فاتح یا غالب قوم کے نظریات سے متاثر ہوتے ہیں اور جانے انجانے میں ان کا شکار ہوجاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہمارا چشمہ ہماری آنکھوں کے مطابق نہیں ہے بلکہ یورپی آنکھوں سے مستعار لیا ہوا ہے۔
(۴) فاتح یا غالب قوم کے نظریات دوسرے سیاق میں قابل عمل نہیں ہوتے اور ان کے ماننے والے عموماً احساسِ کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں اور حقائق کا غلط اورگمراہ کن ادراک کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر چشمہ اگر اپنی آنکھوں کے مطابق نہ ہو تو حقائق مسخ شدہ نظر آتے ہیں۔
(۵)ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نظریے کو جان بوجھ کر قبول کیا جائے جو ہر حالت اور مقام پر ہماری رہنمائی کے فرائض انجام دے سکے۔ بالفاظ دیگر اس چشمے کو جو ہماری نگاہوں پر چڑھ گیا ہے بدل کر ہمیں شعوری طور پر ایک ایسا چشمہ پہننا چاہئے جو ہمیں حقیقت کو ویسا ہی دکھائے جیسا کہ وہ ہے۔