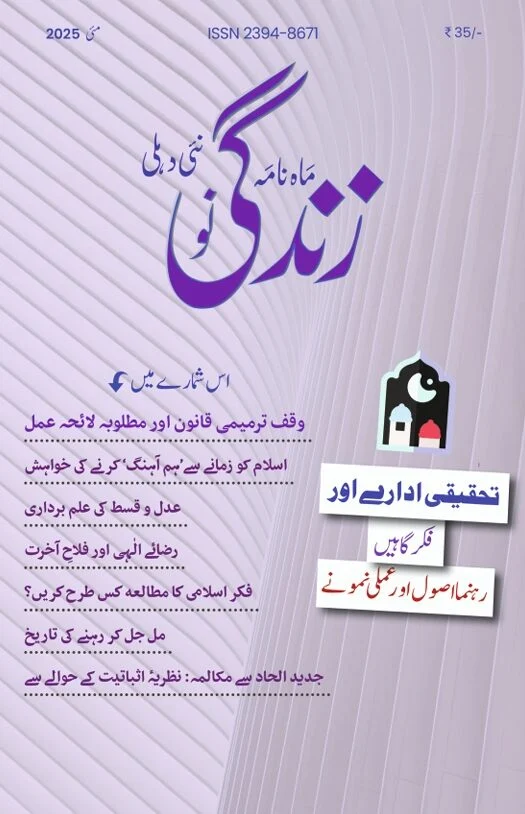اس سے پہلے ہم نے واضح کیا تھا کہ اسلامی تحریک میں جب تعدد واختلاف کی قبیح شکلیں پیدا ہوتی ہیں، جن کا مشاہدہ ہم مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں کرچکے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اسلامی تحریک کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے ہم ان کے اسباب کو بیان کریں گے۔ جب ہم اسباب پر گفتگو کریں گے تو علاج کا بھی تذکرہ ہوجائے گا۔ اس لیے کہ ان اسباب کا ازالہ کرلینا ہی علاج ہے۔ میری جستجو کی حد تک یہ اسباب سات آفتوں پر مشتمل ہیں۔ یہ ساتوں آفتیں کسی ایک کیس میں جمع نہیں ہوتی ہیں لیکن جہاں ایک پائی جاتی ہے وہاں اندیشہ رہتا ہے کہ اس سے دوسری اور تیسری بھی جنم لے۔ یہ آفتیں ایک دوسرے کو جنم دیتی ہیں اگر ان کا فوری تدارک اور علاج نہ کیا جائے۔
پہلی آفت: جماعتوں کے درمیان قطع تعلق
مسلمانوں کے درمیان قطع تعلق شرعًا حرام ہے، وہ افراد کے درمیان ہو یا گروہوں کے درمیان۔ یہ حرمت بڑھ جاتی ہے جب امت پر اس کے اضرار و مفاسد مرتب ہوتے ہیں۔ داعیانِ دین اور اسلامی تحریکات کے قائدین کے درمیان قطع تعلق سے ایسی صورت عام طور سے پیدا ہوجاتی ہے۔
جماعتوں کے درمیان قطع تعلق کبھی بلا ارادہ و اصرار ہوتا ہے، مثال کے طور پر ملک کے حالات باہم ملاقات اور ملنے جلنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ ضرورت اپنی جگہ معتبر ہے۔ جہاں تک ضروری ہو اس کا لحاظ کیا جائے اور جہاں ضروری نہ ہو وہاں قطع تعلق کی کیفیت سے باہر نکل آیا جائے۔
کبھی قطع تعلق محض کوتاہی اور مشغولیت کے نتیجے میں ہوسکتا ہے۔ یہ صورت ہوسکتا ہے حرام کے دائرے میں نہ شمار ہو۔ لیکن اگر یہ کیفیت زیادہ عرصے تک باقی رہے اور کوئی فریق اس سرد مہری کو توڑنے اور قطع تعلق کی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے پیش قدمی نہ کرے تو ہوسکتا ہے کہ اسلامی تحریک بہت سے فائدوں سے محروم ہوجائے۔ مزید یہ کہ اس سے دلوں میں میل آسکتا ہے، بدگمانیوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں تعلقات میں بگاڑ آسکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خراب بات یہ ہے کہ قطع تعلق جان بوجھ کر اور طے شدہ فیصلے کے تحت روا رکھا جائے۔ اس کی ایک وجہ عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ ایک فریق دوسرے کا اعتراف نہیں کرتا اور قطع تعلق کے ذریعے اسے یکسر نظر انداز کردینا چاہتا ہے گویا کہ اس کے وجود ہی کا انکاری ہو۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو فریقوں میں نفرت پیدا ہوجاتی ہے اوران کے دل اسے بھلا نہیں پاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق یا دونوں ہی فریق احساس برتری یا احساس بے نیازی کا شکار ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان تمام ہی صورتوں میں اس قطع تعلق کو جواز حاصل نہیں ہوتا ہے جسے شریعت نے شدید طور سے حرام کیا ہے۔ ہمارے لیے فرمان رسول ﷺ کافی ہے: آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے پشت نہ پھیرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو اور بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بنو۔ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین رات سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ (متفق علیہ، انس بن مالک)
اگر یہ سخت تاکید عام مسلمانوں کے سلسلے میں اور ان کے معمول کے تعلقات کے بارے میں ہے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا جو اس امت کے بہترین لوگ مانے جاتے ہیں، یا جنھیں بہترین لوگ ہونا چاہیے؟؟ وہ لوگ جو اسلامی کاز اور دعوتی مشن کے لیے سرگرم ہیں۔ وہ لوگ جن کے قطع تعلق سے عمومی مصالح کے حصول اور عمومی مفاسد کے ازالے کے لیے تعاون کی راہیں بند ہوجاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے قطع تعلق سے دعوت کے جہدکاروں اور رہ نماؤں کے درمیان مشاورت، تبادلہ خیال اور مفاہمت کا عمل رک جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کے قطع تعلق سے صرف اسلامی تحریک ہی نہیں بلکہ پوری امت کے جسم میں فرقہ بندی اور انتشار گہرائی تک سرایت کرجاتے ہیں۔
اسلامی تحریک کے قائدین اور دعوت دین کے کارکنان اپنے درمیان تعلق کی حفاظت کریں، قطع تعلق اور علاحدگی کی تمام صورتوں پر روک لگائیں اور کم از کم باہمی مفاہمت اور تعاون کی ادنی سطح کو برقرار رکھیں۔ یہ وہ فریضہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا۔
دوسری آفت: خواہشات کا دور دورہ
اکثر خواہشات جو انسانوں پر اور ان کے فکر و عمل پر راج کرتی ہیں، ان کی فطری بنیاد انسانی نفوس کے اندر ہی ہوتی ہے اور اصل میں ان کا ایک ایجابی کردار بھی ہوتا ہےاگر ان کا درست استعمال کیا جائے اور انھیں اعتدال اور ڈسپلن کے اندر رکھا جائے۔ لیکن جب وہ نگرانی اور ڈسپلن کے دائرے سے باہر نکلتی ہیں اور بے قابو ہوجاتی ہیں تو انسان کی زندگی اور اس کی شخصیت کی ہر چیز کو بگاڑنے کا سبب بن جاتی ہیں۔
خواہشات کی انسانی نفوس میں گہری بنیاد ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ خاموشی سے اور اپنے آپ اندر ہی اندر نشوونما پاتی اور توانا ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان پر اس طرح غالب آجاتی ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی لیے ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام شروع کرتے ہیں، دعوتی اور رفاہی منصوبوں کا آغاز کرتے ہیں، تو اس وقت وہ صدق واخلاص اور بے نفسی سے مالا مال ہوتے ہیں، پھر نگرانی اور خود احتسابی کی غیر موجودگی میں خواہشات حرکت میں آتی ہیں۔ وہ غیرت و حمیت اور جوش و قربانی کے لباس میں اپنا کھیل کھیلتی ہیں۔ اکثر تو انسان یہ تسلیم ہی نہیں کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی خواہشات کے زیر اثر آرہا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے بارے میں صرف اتنا جانتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹانے، جدوجہد کرنے اور قربانی دینے کے لیے اٹھا ہے۔ اس کا اصرار یہی ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کررہا ہے دراصل اللہ کے راستے میں اور اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں کررہا ہے، لیکن وہ خواہشات نفس کے زیر اثر آچکا ہوتا ہے۔
اجتماعی کاموں کے ماحول میں جو خواہشات عام طور سے پنپتی ہیں وہ یہ ہیں: نمایاں ہونے اور شہرت پانے کی طلب، سرداری اور قیادت کی چاہ، زیادہ سے زیادہ معتقدین اور متبعین کی خواہش، دوسرے ہم رتبہ افراد سے آگے نکل جانے کا جذبہ۔
جب ہم تباہ کن تنظیمی تعدد کی بات کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواہشات بسا اوقات ایسی کشمکش اور مقابلہ آرائی کی طرف لے جاتی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی وحدت، اخوت اور اخلاق سب پارہ پارہ ہوجاتے ہیں۔
شریعت نے خواہش نفس کے موضوع کو خاص اہمیت دی، اس سے بہت زیادہ خبردار کیا اور اسے کنٹرول کرنے اور قابو میں رکھنے کی تاکید کی۔ امام ابواسحاق شاطبی نے اصولی رہ نمائی کی کہ ‘‘ شریعت کے وجود کا شرعی مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کی خواہشات کے اثر سے نکالا جائے تاکہ وہ جس طرح بے اختیاری طور پر اللہ کا بندہ ہے، اختیاری طور پر بھی اللہ کا بندہ ہوجائے۔’’
معاصر علما اور داعیانِ اسلام نے بھی اس موضوع پر توجہ دی اور اسلامی تحریک پر اس کے پڑنے والے نقصانات سے ہوشیار کیا۔ کیوں کہ انھوں نے یہ محسوس کیا کہ اسلامی تحریک کی صفوں میں خواہشات کے پھیل جانے سے تحریک کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور اس کے بہت سی کوششیں، کاوشیں اور تعلقات خرابی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ڈاکٹریوسف قرضاوی کہتے ہیں:
‘‘اسلامی جماعتوں اور تحریکوں میں جو طرح طرح کے اختلافات پیدا ہوئے اور ہوتے ہیں، اسی طرح ایک جماعت کے اندر مختلف گروپوں کے درمیان اختلافات کی بات ہے، یا قیادت پر فائز افراد کے درمیان اختلافات کی بات ہے، شدید افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے بیشتر اختلافات میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کی اصل وجہ ذاتی معاملات اور شخصی اہداف ہوتے ہیں، اگرچہ انھیں اسلام کے مفاد یا جماعت کے مفاد وغیرہ کے لیے فکر مندی کے غلاف میں اس طرح لپیٹ دیا جاتا ہے کہ خود اس انسان پر اصل حقیقت مخفی ہوجاتی ہے، اس کا نفس اس کی بدعملی کو خوب صورت بناکر پیش کرتا ہے اور وہ اسے واقعتًا اچھا باور کربیٹھتا ہے۔’’
اس آفت کا تنہا علاج وہی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا اور نہ کوئی اس میں بحث کرسکتا ہے، اور وہ ڈاکٹر قرضاوی کے الفاظ میں:
‘‘ صرف ایک اللہ کے لیے اخلاص، حق سے بے لوث تعلق، نفس کے ساتھ مجاہدہ یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات اور دوسروں کی خواہشات سے پوری طرح آزاد ہوجائے۔’’
لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، لوگوں کی ضرورت یہ ہے کہ وہ مسلسل اپنے نفس اور نفس کے محرکات کی نگرانی اور احتساب کرتے رہیں۔ انھیں ایک ایسے اجتماعی ماحول کی ضرورت ہے جہاں بیداری ہو اور خواہشات کا گزر منع ہو۔ ایسا ماحول نہ ہو جو خواہشات کو پنپنے، خواہشات کے لیے جواز تراشنے اور خواہشات پر ملمع چڑھانے کے لیے سازگار ہو۔
تیسری آفت: عصبیتوں کا بخار
لوگ جن چیزوں سے نسبت رکھتے ہیں ان کے لیے یک گونہ عصبیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ ایک عام اور قدیم صفت ہے۔ لوگ اپنے ملکوں کے لیے، وطنوں کے لیے، قوموں کے لیے، آباء واجداد کے لیے، شیوخ اور قائدین کے لیے، پارٹیوں اور مسلکوں کے لیے عصبیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جن چیزوں کی نسبت ان کی طرف ہوتی ہے ان کے لیے بھی عصبیت رکھتے ہیں، جیسے ان کی اولاد، ان کے پیروکار، ان کے افکار و اعمال۔ یہ کیفیت اس طرح انسانوں میں رچی بسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ ایسا ہویا نہ ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کیفیت کا زور اس وقت تک نہیں ٹوٹتا ہے جب تک بہت زیادہ تربیت، علاج اور اخلاقی وعلمی ترقی سے نفس کو گزارا نہ جائے۔
اسلامی تحریکات جب اس خرابی کے علاج میں لاپروای کرتی ہیں اور اسے بڑھنے سے روکنے کی تدابیر اختیار نہیں کرتی ہیں تو یہ خرابی مختلف شکلوں میں ان کے اندر پھیلتی ہے۔ ملکی عصبیت، علاقائی عصبیت، جماعتی عصبیت، گروہی و مسلکی عصبیت، جماعت کے مختلف موقفوں اور رایوں کے حوالے سے عصبیت، قائدین کے حوالے سے عصبیت۔۔ یہ عصبیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، توانا اور خطرناک ہوجاتی ہے جب جماعت کے قائدین اس کی سرپرستی کرنے لگیں اور اسے غذا اور قوت فراہم کرنے کا کام کریں۔
اسلامی تحریک نے اپنی بعض جماعتوں کے اندر عصبیتوں کے کڑوے پھلوں کو چکھا ہے۔ خاص طور سے جماعتی عصبیت(ہماری جماعت سب سے افضل ہے اور بس اسی کا راستہ درست اور قابل اتباع ہے) اور قیادت کے لیے عصبیت (ہمارے قائدین سب سے بہتر ہیں، ان کی خوبیاں لاجواب ہیں، ان کے افکار اور رائیں غلطی سے پاک اور تنقید سے بالاتر ہیں)۔
جب عصبیت نفس میں سرایت کرجاتی ہے تو جس سے عصبیت کا تعلق ہوتا ہے وہ سب سے اچھا قرار پاتا ہے، دل اس کی تائید و نصرت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، وہ ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ اور ہر طرح کے عیب سے پاک نظر آتا ہے، اس کی غلطی غلطی نہیں لگتی اور خامی خوبی لگتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے مقابل جو بھی ہو وہ نگاہ میں بالکل نہیں جچتا۔ اس کی چھوٹی خامی بھی بہت بڑی نظر آتی ہے۔
جماعتی عصبیت کو نشوونما دینے والی ایک چیز مدح و تعریف کا لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے۔ جماعت سے وفاداری کے نام پر اور اس کے لیے شرعی جواز تراش کر جماعت کی ہر طرح سے ستائش کی جاتی ہے، اس کی ہر ادا اور فیصلے کی ملمع کاری کی جاتی ہے اور اپنے کاموں کا کبھی جائزہ نہیں لیا جاتا، اپنی روش کا کوئی احتساب نہیں کیا جاتا،فیصلوں اور ان کے نتائج کے حوالے سے کسی تنقید کی گنجائش نہیں رکھی جاتی۔
حقیقت یہ ہے کہ احتساب و جائزہ اور نظر ثانی و تصحیح کا عمل تو جماعت کے افراد اور قائدین سب کے درمیان بڑے وسیع پیمانے پر ہونا ضروری ہے۔ تبھی اس کے مثبت اور تعمیری نتائج سامنے آئیں گے اور اندھی عصبیت جیسے انحرافات سے بچاؤ ممکن ہوسکےگا۔
چوتھی آفت: علمی نگاہ کا فقدان
خواہشوں اور عصبیتوں کے ساتھ جو آفت ہمیشہ رہتی اور ساتھ ہی گزر بسر کرتی ہے وہ علمی نگاہ کا فقدان ہے۔ علمی نگاہ اندھی عصبیت کی باتوں میں دور تک جانے سے روکتی ہے اور خواہشوں سے بار بار ٹکر لیتی اور ان کا پردا فاش کرتی ہے۔ خواہشیں اور عصبیتیں انسان کو اندھا بہرا بنادیتی ہیں، حقائق کو چھپاتی اور پیمانوں کو الٹ دیتی ہیں، جب کہ علمی نگاہ عدل کے میزان کو قائم کرتی ہے، حقائق کو بے نقاب کرتی ہے اور انھیں ان کی صحیح شکل میں پیش کرتی ہیں۔ خواہشیں اور عصبیتیں علمی دلائل کو کنارے لگادیتی ہیں اور ان کو بے اثر کردیتی ہیں جب کہ علمی نگاہ دلیل کے ساتھ رہتی ہے، جدھر دلائل لے جاتے ہیں ادھر لے جاتی ہے۔ خواہشیں اور عصبیتیں سماعت، بینائی اور دل سب کو معطل کردیتی ہیں، بیرونی کے الفاظ میں: ‘‘عصبیت دیکھنے والی آنکھوں کو اندھا کردیتی ہے، سننے والے کانوں کو بہرا کردیتی ہے اور ایسی چیزوں کے ارتکاب پر آمادہ کرتی ہے جن کو صحیح باور کرنےکی بھی عقل اجازت نہیں دیتی ہے۔’’
جب کہ علمی نگاہ علم کے ان ذرائع کی حفاظت کرتی ہے، ان سے رہ نمائی لیتی ہےاور ان کے عمل کو بہتر سے بہتر رخ دیتی ہے۔
معاملہ شریعت اور اس کے احکام کے فہم سے متعلق ہو، صورت حال کے فہم سے متعلق ہو، مستقبل کے بارے میں اندازہ قائم کرنے سے متعلق ہو یاکسی شخص کی قدر وقیمت متعین کرنے کے بارے میں ہو، علمی نگاہ ہمیشہ دلیل طلب کرتی ہے اور اس کے مطابق رائے قائم کرتی ہے۔ لیکن جب خواہشوں کا دور دورہ ہو اور عصبیتوں کا راج ہو، خواہ وہ جماعتی عصبیت ہو، جماعتی مفاد کے لیے عصبیت ہو، جماعت کی قیادت اور اس کے فیصلوں کے لیے عصبیت ہو، توہوتا یہ ہے کہ ہر معاملے میں علمی نگاہ پس پشت چلی جاتی ہے، سطحیت اور عجلت پسندی حاوی ہوجاتی ہے۔ پہلے سے بنی ہوئی رائیں اور خود ساختہ مسلمات کی کارفرمائی ہوتی ہے، جن پر نظرثانی یا تنقید کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی علمی اپروچ قابل نفرت ہوتی ہے جو ان رایوں اور مسلمات کو زک پہنچائے، اپنے فیصلوں کی راہ میں روڑا بنے یا اب تک چلی آرہی پالیسیوں میں خامی کی نشان دہی کرے۔ اس طرح کے ماحول میں ایسے تمام لوگ جو مختلف ڈھنگ سے سوچتے یا غیر جانب دار ترازو سے تولتے ہیں، وہ دور کردیے جاتے ہیں یا خود دور ہوجاتے ہیں۔ اس طرح جماعت علمی نگاہ سے دور ہوتی جاتی ہے اور علمی ماحول اس کے درمیان سے برخاست ہوتا جاتا ہے۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم کی آواز رندھی ہوئی، دبی ہوئی اور شکست کھائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہمارےاعمال، افکار، اندازوں اور فیصلوں پر اوہام، جذبات، خواہشات اور عصبیتوں کا راج ہوتا ہے۔
پانچویں آفت: انصاف پر قدرت کا فقدان
نا انصافی کا مکمل ازالہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص سے (معصومین کے سوا) نا انصافی کا ارتکاب ہوسکتا ہے۔ فیصلوں میں، جائزوں میں، رویوں میں۔ بعض سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو بعض سے کم یا بہت کم۔ میرا مقصد یہ ہے کہ بے لوث منصفانہ تفکیر کی قدرت اور منصفانہ رویے اختیار کرنے کی قدرت کا فقدان ہے۔
غرض یہ کہ جس آفت کے بارے میں یہاں بات ہورہی ہے وہ گذشتہ تین آفتوں کے جمع ہوجانے کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام آفتیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ایک دوسرے کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ جب خواہش و عصبیت کا مارا انسان انصاف کی قدرت کھوبیٹھتا ہے، درست نتیجہ نکالنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوجاتا ہے تو پھر شرعی دلیلوں کا سہارا اس کے کام نہیں آتا۔ کیوں کہ علمی دلائل کے ساتھ صحیح تعامل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خواہش و عصبیت کی بیڑیوں سے آزادی حاصل کی جائے۔ امام شاطبی لکھتے ہیں: ‘‘ جب خواہش نفس میں داخل ہوجاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان متشابہ کے پیچھے چلتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی اختلافی رائے کو کسی طرح درست قرار دے کر غالب ہوجائے۔ اس کے نتیجے میں افتراق، قطع تعلق، عداوت اور بغض کا ظہور ہوتا ہے، کیوں کہ خواہشیں الگ الگ ہوتی ہیں اور وہ باہم متفق نہیں ہوتیں۔ شریعت آئی ہی اس لیے ہے کہ خواہش نفس کا مکمل قلع قمع کرے۔ لیکن جب خواہش ہی دلیل کا جز بن جائے، تو پھر خواہش کے مطابق ہی نتیجہ برآمد ہوگا۔’’
اس طرح کی کیفیت میں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مختلف جماعتوں، مسلکوں اور پارٹیوں سے وابستہ لوگ ہر حال میں اپنی چیز کی تائید، تعظیم اور توجیہ کرتے ہیں اور دوسروں کی چیزوں کی ہر حال میں مخالفت، تحقیر اور تنقیص کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دوریاں بڑھتی ہیں، دلوں میں خرابی آتی ہے، بے اعتمادی بڑھتی ہے اور بدگمانی میں اضافہ ہوتا ہے۔
آج بعض اسلامی جماعتوں کے وابستگان کے درمیان جو کشاکش ہے، وہ پرانے زمانے میں کلامی فرقوں سے وابستہ لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ علامہ ابن قیم اس کے بارے میں بتاتے ہیں: ‘‘ فضل و عقل رکھنے والا غور کرے کہ رایوں کی نصرت، ان کے لیے عصبیت، ان کے تقاضوں کی پابندی اور ان رایوں کے علم برداروں سے حسن ظن( جس کے نتیجے میں ان کی خرابیاں بھی خوبیاں نظر آئیں) اور ان کے مخالفین سے بدظنی( جس کے نتیجے میں ان کی خوبیاں بھی خامیاں نظر آئیں)، ان کے اس رویے نے ان کی فطرت کو کتنا بگاڑ دیا ہے۔ یہ رویہ رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو (قرآنی تعبیر کے مطابق) سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اساس پر ہیں، حالاں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ’’
ابن قیم ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ‘‘ یہ وہ آفت ہے جس سے وہی بچ پاتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہو اور جسے اللہ اس کی توفیق دے کہ وہ حق کی پیروی کرے، خواہ حق کہیں بھی ہو اور کسی کے پاس بھی ہو۔ لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حق ہمیشہ کے لیے اس کے گروہ اور اس کے مسلک والوں کے لیے وقف ہوگیا ہے اور دوسروں کے لیے بالکل منع ہوگیا ہے، (حالاں کہ ممکن ہے کہ وہ دوسرے اس سے زیادہ حق و صواب سے قریب ہوں) تو سمجھ لو کہ وہ خیر کثیر سے محروم ہوگیا اور عظیم ہدایت کا سرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ’’
غرض انصاف کی صفت کے فقدان کی یہ آفت آج کی اسلامی تنظیموں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایسی جگہ پائی جاتی ہے جہاں عصبیت اور خواہشات کا دور دورہ ہوتا ہے اور بے لوث علمی نظر مفقود ہوتی ہے۔ آج ہم یہ آفت سیاسی، جماعتی اور نظریاتی بیانیوں میں صاف دیکھتے ہیں۔ رابرٹ ایچ تھالیس (Robert H. Thouless ) اپنی کتاب (Straight and Crooked Thinking)میں اس آفت کی بہتر وضاحت کرتا ہے۔ بطور مثال وہ کہتا ہے: ‘‘جب ہماری پارٹی کا کوئی مقرر جوش و بلاغت سے بھرپور تقریر کرتا ہے تو ہم اسے بلاغت کا شہسوار کہتے ہیں، لیکن جب مخالف پارٹی کا مقرر اسی طرح کی تقریر کرتا ہے تو ہم اسے منھ پھٹ کہتے ہیں۔ حزب مخالف کی تجاویز اگرچہ عملی ہوں، مگر ہم طنزیہ کہتے ہیں کہ یہ تو جھاڑ پھونک والوں کی زبان میں ہر مرض کا علاج ہیں۔ گویا ان سے اسی طرح تنفر پیدا کرنا چاہتے ہیں جس طرح لوگوں میں جھاڑ پھونک سے تنفر پایا جاتا ہے۔ جن رایوں سے ہمیں اتفاق نہیں ہوتا ان کی تائید میں اگر کوئی زیادہ جوش دکھائے تو اسے انتہا پسند کے ٹیگ سے نواز دیتے ہیں لیکن ہماری پارٹی کے کچھ لوگ اگر اسی طرح بہت جوشیلے نظر آئیں تو انھیں حق کے متوالے قرار دیتے ہیں۔ ’’
یہ بے لوثی، اور عدل و انصاف کے فقدان کے کچھ مظاہر ہیں، جو ایسے گروہوں کے یہاں دیکھے جاسکتے ہیں جو عصبیت، نفس پرستی اور علم بے زاری سے معمور ہوتے ہیں۔
‘‘ تمھارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم، اس کی مدد کرو ’’ یہ لوگ اپنے عمل سے اس مقولے کی جاہلی تفسیر کرتے ہیں اور اس پر مزید اضافہ یہ کرتے ہیں کہ ‘‘ تمھارا حریف غلطی پر ہو یا بر حق ہو، اس کی مخالفت ضرور کرو’’۔ دو یا دو سے زیادہ فریقوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف ردّعمل کا یہ رویہ اتنی بار دوہرایا جاتا ہے کہ پھر وہی نارمل اسلوب قرار پاتا ہے۔ سب اس کے عادی اور اس سے مانوس ہوجاتے ہیں۔ بلکہ یہ عمل باہمی اختلافات، نزاعات اور تفرقے کا ایک مستقل سرچشمہ بن جاتا ہے۔
بے لوث اورانصاف پسند علمی نگاہ کا موقف تو یہ ہوتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، وہ تمھارا بھائی ہو یا دشمن ہو، ظالم کا سامنا کرو وہ تمھارا بھائی ہو یا دشمن ہو، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دو چاہے وہ تمھارا حریف کیوں نہ ہو اور جو باطل پر ہو اس کی مخالفت کرو چاہے وہ تمھاری پارٹی یا قوم کا کیوں نہ ہو۔ یہی اسلام کا موقف ہے۔
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى [الأنعام: 152]
(جب کہو تو عدل کی بات کہو خواہ رشتے داروں کا معاملہ کیوں نہ ہو)
مزید دیکھیں [النساء: 135] اور [المائدة: 8]
چھٹی آفت: تنقید و جائزے کی استعداد کا فقدان
یہ آفت پچھلی چاروں آفتوں کے ساتھ گتھی ہوئی ہے۔ یہ ان سے خوراک پاتی ہے اور انھیں خوراک دیتی ہے۔ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ایک طرف یہ خود پسندی کو پروان چڑھاتی ہے، اپنے آپ کے معصوم و پاک باز ہونے کا گہرا یقین پیدا کرتی ہے اور وہیں اپنی ذات کی عصبیت کو شدید تر کرتی ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے، خواہ وہ افراد ہو یا جماعتیں، وہ اپنے اوپر ہونے والی ہر تنقید کو اپنے ساتھ دشمنی، اپنے خلاف اعلان جنگ اور اپنی سرحد کی بے حرمتی قرار دیتے ہیں۔
وہ اپنے ناقدین سے اعلان جنگ کرتے اور انھیں مناسب طریقے سے سبق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینٹ کے جواب میں پتھر والی سوچ حرکت میں آتی ہے۔ اس طرح جنگ چھڑ جاتی ہے۔اختلافات گہرے ہوتے جاتے ہیں۔
یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ تعریف، ستائش اور تائید کے عادی ہوگئے ہوتے ہیں، کسی طرح کی تنقید، اعتراض یا نصیحت کا انھیں کوئی تجربہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تنقید، اختلاف، مخالفت اور غلطی کی نشان دہی کے سلسلے میں ان کے اندر شدید قسم کی حساسیت پیدا ہوجاتی ہے۔ حقیقت میں تو یہ گھمنڈیوں اور تکبر کے ماروں کی صفت ہے جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے: وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِینَ [الأعراف: 79]، (لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے)
علامہ مودودیؒ نے درست کہا: ‘‘ تنقید سن کر طیش میں آجانا کبر اور غرور نفس کی علامت ہے۔ ’’
داعیانِ اسلام کا مقام تو اور بھی بلند ہے، عام اہل اسلام سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے اور یہی ان کے شایان شایان بھی ہے کہ وہ تنقید اور نصیحت کو کشادہ ظرفی اور خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہیں اور مدح و ستائش کے سلسلے میں محتاط اور ہوشیار رہیں۔ ناقد وناصح اگر فائدہ نہیں پہنچائے گا تو نقصان بھی نہیں کرے گا جب کہ مدح و ستائش کرنے والا اگر نقصان نہ پہنچائے تو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا، بلکہ زیادہ تر تو نقصان ہی کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ناقد وناصح کو خوش آمدید کہنا چاہیے خواہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کی تنقید غلط ہے اور اس کی نصیحت بے جا ہے۔ کیوں کہ اس طرح ہم ایک طرف تو اصولی طور پر تنقید کو سراہنے والے ہوں گے، دوسری طرف خود نصیحت کے عمل کی ستائش کرنے والے ہوں گے، اس سے قطع نظر کہ اس مسئلے میں درست یا نا درست کیا ہے۔
اور جس کی تنقید کا درست ہونا اور گرفت کا صحیح ہونا ہم پر واضح ہوجائے، اس کے لیے ہماری خوشی اور شکر گزاری کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی تربیت کرکے خود کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ ہم تنقیدیں قبول کریں اور تنقید کی غلطی کو تلاش کرکے اس کا جواب دینے کی کوشش کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کتنی درست اور کس قدر مفید ہے۔ ہمیں اپنی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ جس شجاعت اور بے باکی کے ساتھ ہم اپنی رائے اور موقف کا اعلان کرتے ہیں، اسی شجاعت اور بے باکی سے اپنی غلطی کا اعتراف اور اعلان بھی کریں، جیسے ہی وہ غلطی ہم پر واضح ہوجائے۔ اس طرح ہم خود کو معصوم عن الخطا ہونے کے احساس سے آزاد کرسکیں گے اور دوسروں کو اس خوف سے نجات دلاسکیں گے کہ اگر وہ ہم پر تنقید کریں گے یا ہمیں مشورہ دیں گے، تو ہماری طرف سے انھیں تہمتوں اور عداوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غرض ہم اس طرح دشمنی کا ایک دروازہ بند کرسکیں گے۔
اس سلسلے میں ایک شان دار مثالی واقعہ وہ ہے جسے قاضی ابوبکر بن عربی نے بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ محمد بن قاسم عثمانی ایک بار شیخ ابوالفضل جوہری کی مجلس میں تھے۔ شیخ صاحب نے درس میں کہا: نبی ﷺ نے تو طلاق بھی دی، ظہار بھی کیا اور ایلاء بھی کیا۔ عثمانی کہتے ہیں کہ جب وہ نکلے تو میں ان کے پیچھے چلا۔۔ میں نے ان سے کہا: آج میں آپ کی مجلس میں آیا تھا کہ آپ کی برکت حاصل ہوگی۔ یہاں میں نے آپ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے طلاق دی تھی، میں نے سچ مان لیا، آپ نے کہا اللہ کے رسول ﷺ نے ایلاء کیا تھا، وہ بھی میں نے سچ مان لیا۔ پھر آپ نے کہاکہ رسول اللہ ﷺ نے ظہار کیا تھا، تو میں چونک گیا۔ یہ تو نہیں ہوا تھا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ کیوں کہ ظہار تو ایک قولی برائی اور جھوٹ کی ایک قسم ہے، ایسی بات نبی ﷺ سے سرزد نہیں ہوسکتی۔ یہ سن کر انھوں نے مجھے گلے لگایا، میرے سر کو بوسہ دیا اور کہا: میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تمھیں اس کا بہترین صلہ دے، تم بہترین معلم ہو۔
دوسرے دن شیخ صاحب نے لوگوں کے درمیان سے پکار کر عثمانی کو بلایا اور کہا کہ منبر کے پاس آؤ، اس طرح سب لوگوں نے انھیں دیکھ لیا، پھر کہا: دیکھو میں تمھارا معلم ہوں اور یہ میرا معلم ہے۔ کل میں نے تم لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے طلاق بھی دی، ایلاء بھی کیا اور ظہار بھی کیا۔ تم لوگوں میں سے کسی نے اس پر غور نہیں کیا اور میری تردید نہیں کی۔ جب کہ یہ صاحب میرے پیچھے گھر تک آئے اور مجھ سے یہ بات کہی۔ پوری بات بتانے کے بعد شیخ صاحب نے کہا: میں کل کی بات سے توبہ کرتا ہوں اور حق بات قبول کرتا ہوں۔ میری کل کی بات سننے والوں میں جو آج موجود ہیں وہ میری وہ بات کہیں اور نقل نہ کریں اور جو آج نہیں ہیں انھیں موجود لوگ بتادیں۔ اللہ عثمانی کو بہتر صلہ دے۔ اس کے بعد وہ عثمانی کے لیے دعا کرتے رہے اور لوگ آمین کہتے رہے۔
اس واقعہ کو نقل کرکے قاضی ابن عربی تبصرہ کرتے ہیں: ‘‘تم پر اللہ کی رحمت ہو، ذرا دیکھو اس پختہ دین داری کو۔ دیکھو کہ ایک شخص جس کا بلند مقام و مرتبہ ہے، جس کی عظمت کا شہرہ ہے، وہ کس طرح سر عام ایک گم نام آدمی کے علم کا اعتراف کررہا ہے۔ جس کے بارے میں یہ نہیں پتہ کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ ایسے نمونے کو اختیار کرو یہی دانائی کا راستہ ہے۔’’
ساتویں آفت: شرانگیزی پر کان دھرنا
نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کو حجة الوداع کے خطبے میں جو آخری نصیحتیں کی تھیں اور بعد کی امت کے لیے انھیں جاوداں کردیا تھا، ان میں ایک نصیحت یہ تھی: ‘‘بلاشبہ شیطان اس سے تو مایوس ہوچکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں گے، لیکن انھیں آپس میں لڑانے کے سلسلے میں وہ پر امید ہے۔’’ (صحیح مسلم)
اس سے معلوم ہوا کہ اہل توحید شرک اور بت پرستی سے اگر محفوظ ہو بھی گئے، تو آپس کی شر انگیزی، عداوت خیزی اور اشتعال پروری سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور خاص کر دینداروں کے درمیان جھگڑے ڈالنے کی بات کتنی خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں انھیں کسی اور چیز نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، جس قدر نقصان ان کی باہمی چپقلشوں اور جھگڑوں نے پہنچایا۔
علما و قائدین کے درمیان جھگڑے لگانے کا کام کبھی جاہل پیروکاروں اور حامیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کرتے اور رائی کا پہاڑ بناتے ہیں۔ اشتعال انگیزی والی صحیح غلط خبریں اچکتے اور پھیلاتے ہیں۔ مخالف گروہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں گویا وہ ان کی جماعت کے لیے ہی نہیں اسلام کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے۔
کبھی جھگڑے لگانے کا کام ایسے لوگ کرتے ہیں جو اسی مقصد سے جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کی خاطر دشمنی اور لڑائی کی آگ بھڑکاتےاور ٹکراؤ کی فضا تیار کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پر جماعت کے لیے غیرت وحمیت کا نقاب پڑا ہوتا ہے اور ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ جماعت کی نصرت اور جماعت کے مخالفین کی سرکوبی کے لیے نہایت مخلص ہیں۔ بسا اوقات یہ گروہ پہلے والے گروہ کی تائید اور تعاون حاصل کرلیتا ہے۔ پھر نیتیں مختلف اور افعال یکساں ہوجاتے ہیں۔
جب کسی جماعت اندر یہ دو گروہ مل جاتے ہیں تو جھگڑے لگانے کا کام زوروں پر ہوتا ہے۔ اندر سے شیطان یہ کام کرتا ہے اور باہر سے بدنیت انسان اسے انجام دیتے ہیں۔
کبھی بیرونی دباؤ اور کوششیں بھی اس میں شامل ہوجاتی ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ شخصیات اور جماعتیں بتدریج ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی جنگ میں ملوث ہوجائیں۔ یہ مخالف بیان بازیاں کبھی تو کتابوں اور مقالوں کی صورت اختیار کرلیتی ہیں۔
کبھی اسلامی تحریکات و رجحانات کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے کانفرنسوں اور مناظروں کا استعمال کیا جاتے ہیں، یہ بارودی سرنگوں کی طرح ہوتے ہیں۔
اس موقع پر یاد آتا ہے کہ قاضی عیاض نے ہارون رشید کی ایک مجلس کا ذکر کیا، اس مجلس میں امام مالک تھے اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد قاضی ابویوسف بھی تھے۔ ہارون رشید نے امام مالک سے خواہش ظاہر کی کہ قاضی ابویوسف کے ساتھ ان کا ایک مناظرہ ہوجائے۔ امام مالک نے کہا: ‘‘ علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے جانوروں اور مرغوں کی طرح لڑانے کا کام لیا جائے۔’’
ہمارے علما، دعاة اور قائدین کو اس بصیرت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ انھیں سمجھنا چاہیے کہ کون سے مناظرے اور ڈبیٹ علمی ہیں اور کون سے محض سازشوں کا شاخسانہ ہیں تاکہ انھیں آپس میں لڑایا جائے جس طرح بچے اور بازاری لوگ مرغے اور جانور لڑاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلامی شخصیات کے درمیان سیدھا تصادم تو نہیں ہوتا لیکن میڈیا والے ان سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور ایسے انٹرویو لیتے ہیں، جن کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں نکل آئیں جن سے کسی کی دل شکنی ہو، کسی کے جذبات مجروح ہوں، کسی کے اوپر حرف آئے اور انھیں اشتعال انگیزی کا موقع مل سکے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ گفتگو اور مذاکرے نہیں ہونے چاہئیں، تنقیدوں اور مشوروں کا دروازہ بند کردیا جائے۔ یہ سب تو ضرور ہونا چاہیے، تاہم نفس اور شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہتے ہوئے، جن میں گرفتار ہوکر انسان مخالفت کی لو تیز کردیتا ہے، غیر محتاط تعبیریں استعمال کرتا ہے اور شدید عمل اور ردعمل کے نتیجے میں مرغوں اور بھینسوں کی لڑائی کا تماشا ہوتا ہے۔
غرض یہ وہ سات ہلاکت خیز آفتیں ہیں، جو اگر مسلم جماعتوں پر مسلط ہوجائیں تو ان کے تعلقات، ان کی اخوت و محبت اور ان کی وحدت کو پارہ پارہ کردیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، طاقت ختم ہوجاتی ہے، توانائیاں بکھر جاتی ہیں اور سارا کام ٹھپ پڑجاتا ہے۔
مشمولہ: شمارہ مارچ 2025